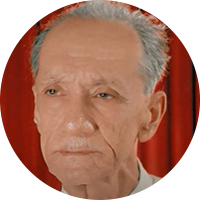غالب اور ہم
ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج
میں عندلیب گلشن ناآفریدہ ہوں
عظیم شخصیتوں کی تین قسمی ہیں۔ کچھ لوگ توایسے ہوتے ہیں جو خود کوئی کارنمایاں انجا م نہیں دیتے لیکن جواپنی نسل اور اس کے توسط سے بعدکی نسلوں کے لئے موثرقوت ثابت ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے وجود سے دوسروں کے دل ودماغ میں تخلیق واکتسابات کاولولہ پیدا ہوتاہے یعنی ان شخصیتوں کی عظمت یہی ہے کہ وہ اپنے ہم عصروں کوکچھ کرکے یادگار چھوڑجانے کی ترغیب دیں اوران کے تخلیقی جذبہ کو بے ساختہ ابھاریں اور اپنے کوکچھ نہ کرسکنے کا کفارہ اداکریں۔
کچھ بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جوخود اپنی جگہ ایک قوت ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے لئے موثرنہیں ہوتے۔ اس کاسبب یاتو یہ ہوتاہے کہ ان روشن شخصیتوں سے جوشعاعیں پھوٹتی ہیں ان کا دائرہ اثرتنگ ہوتا ہے اور وہ ان شخصیتوں کے گردہالہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ یاپھر اگریہ شعاعیں دورتک پہنچتی بھی ہیں تووہ اتنی تیز اور گرم ہوتی ہیں کہ دوسرے ان کی تاب نہیں لاسکتے اور اپنی خواہش اورکوشش کے باوجودان کی بجائے خود عظیم شخصیتوں کے اثرات اپنے اندرجذب نہیں کرپاتے۔
لیکن بڑے لوگوں کی ایک تیسری قسم بھی ہے۔ اس قسم کے لوگ بڑی چیدہ او ر موثر شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ خود تواپنی جگہ تخلیقی یا اختراعی توانائی رکھتے ہی ہیں لیکن ان کے اندریہ قوت بھی ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنے معاصرین کی قابلیتوں کونئے انداز سے متاثرکریں بلکہ نسلا بعد نسل ہر زمانہ میں ہونہار نوجوان ذہنوں میں اپنے یادگار کارناموں کے اثرات سے فکروبصیرت کونئی جلادیتے رہیں اوراختراع واکتسابات کے میدان میں نئے امکانات اورنئی سمتوں کا احساس پیدا کرتے رہیں۔ ان عظیم شخصیتوں کوہرعہدکا جدیدذہن اپنا ہمدم اورہم قدم پاتاہے اور ہر نوجوان صاحب فکر وتخیل کی طرف اپنے کوکھینچتامحسوس کرتا ہے۔ غالب اکابر کی اسی تیسری برادری میں سے ہیں اور اپناایک خاص مقام رکھتے ہیں۔
اکابرذوق ونظراورمشاہیر فکروفن کواپنے زمانہ سے اکثرکورذذقی اورقدرشناسی کا شکوہ رہاہے۔ سقراط سے لے کر آج تک جولوگ فکری اعتبار سے پیش رفت رہے ہیں ان کونہ صرف اپنے زمانہ کے لوگوں سے شکایت رہی ہے بلکہ ان میں ایسوں کی تعداد کم نہیں جو ستائے گئے ہیں اورجن کو اپنی تخیل کی بدولت جان کی قربانی دینا پڑی ہے۔ انیسویں صدی کے رومانی دورمیں ورڈسورتھ جیسا مطمئن قلب ودماغ رکھنے والا اپنے عہد کی مادیت اوربڑھتی ہوئی زرپرستی کا روناروگیا ہے۔ اس کے خیال میں سوداگرانہ ذہنیت اورتاجرانہ لین دین نے ہماری قوتوں کوضائع کردیاہے اورہم کو اس قابل نہیں رکھاہے کہ ہم ان برکتوں کومحسوس کرسکیں جو قدرت نے ہمارے لئے مہیا کی ہیں۔ دوسری رومانی نسل کامشہور انگریزی شاعرشیلی اپنے زمانے سے بہت ا ٓگے تھا۔ یہی نہیں بلکہ موجودہ موعودہ الفیہ مسعود کی تمام برکتیں اپنے ہی زمانہ میں دیکھ لیناچاہتا تھا۔ وہ اپنے عہد سے اس قدر برگشتہ اور متنفر ہوا کہ خودکوجلاوطن کرلیا اوراطالیہ میں رہا اور وہیں شبابمیں مرااورجب تک وہ زندہ رہا اس کا وطن اس کوطعن ولعنت کا نشانہ بنائے رہا۔ شیلی فراغت آزادی اورمحبت کا پیغمبرتھا۔
غالب کوبھی زمانہ اور اورابنائے زمانہ سے شکایت رہی جیسا کہ ان کے خطوط اور بعض اردو اورفارسی اشعار سے مترشح ہوتاہے۔ عام خیال یہ تھا کہ ان کا اردوکلام فکر کے اعتبار سے پیچیدہ اور اسلوب کے لحاظ سے غیرمانوس اور دوراز کا رہوتاہے۔ خودغالب کواحسا س تھا کہ ان کاکلام مشکل ہے اور وہ ’’گویم مشکل وگرنہ گویم مشکل‘‘ کی کشمکش میں مبتلاتھے۔ اسی لئے مولوی فضل حق خیرآبادی جیسے مخلصوں کے مشورہ اورتعاون سے وہ انتخاب مرتب ہوا جس کو’’نسخہ حمیدیہ‘‘ کی اشاعت سے پہلے ’’دیوان غالب‘‘ سمجھاجاتا رہا۔ یہ اپنے عہد کے بہتر معزز اور ممتاز لوگ تھے اورغالب کی صلاحیتوں کے معترف تھے۔ اور صدق دل سے چاہتے کہ غالب ک فکری اجتہادات اور اسلوبی اختراعات کم سے کم ارباب علم وفن میں کثیر سے کثیرتعداد کے لئے قابل فہم ہوں اوروہ ان سے فیض حاصل کرسکیں۔
مگرایک گروہ اسے لوگوں کابھی تھا جو باکمال ہستیوں سے صرف اس لئے حسد اور پرخاش رکھتے ہیں کہ خوداپنے اندر کوئی کمال پیدا نہ کرسکے اورجواچھوں کوبرا کہتے ہیں کیونکہ وہ ایساکرنے پر اسی طرح فطرتا مجبور ہیں جس طرح بچھو ڈنک مارنے پر۔ یہ لوگ غالب کی شاعری کو سرتاسرمہمل بتاتے تھے۔ ان کی نیتوں میں فتورتھا۔ اور وہ غالب سے للہی عناد رکھتے تھے۔ یہ گروہ غالب کی مخالفت میں اپنی آواز مشتہر بھی کرتا تھا۔ ایک ہم عصر کا یہ شعر غالب کے اکثر تذکرہ نگاروں نے مثال کے طور پر درج کیاہے۔
کلام میر سمجھے اور زبان میرزا سمجھے
مگران کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے
اورغالب کے ذہن میں یہی لوگ تھے جب انہوں نے یہ اشعارکہے تھے۔
نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پروا
گر نہیں ہیں میرے اشعار میں معنی نہ سہی
حسد سزائے کمال سخن ہے کیا کیجئے
ستم بہائے متاع ہنر ہے کیا کہیئے
غال سوختہ جاں راچہ بگفتار آری
بہ دیارے کہ نہ دانند نظیری زقتیل
آخری دوشعر توذاتی شکایت کے حدود سے نکل کرکلیات بن کرتاریخ تہذیب کے قدیم ترین ادوا ر سے لے کرہمارے اپنے دورتک درست ثابت ہورہے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ اکثریت میں ہیں جو غالب اورنظیری اورقتیل اورواقف کے درمیان کوئی امتیاز نہیں کرتے اور جوغالب جیسی باکمال شخضیتوں کے لئے اپنے دلوں میں حسدکے سوا کوئی دوسرا جذبہ نہیں پاتے۔
غالب اپنے حاسدوں میں کسی کواپنا ’’ہم فن‘‘ اور ’’ہم نوا‘‘ نہیں سمجھے تھے اوربظاہر ان کے ایرادوتنقیص کی طرف سے بے پروانظرآتے تھے لیکن ان کے اردوکلام پراعتراضات کی بوچھاڑنے ان کواتنا تنگ کیاکہ انہوں نے ’’سوادریختہ‘‘ کے ایک دوجزو یعنی ’’مجموعہ اردو‘‘ کواپنا ’’بے رنگ‘‘ کلام کہہ دیا اوراپنی فارسی شاعری کونقش ہائے رنگ رنگ کا عنوان دے کر اپنے لئے باعث فخر قرار دیا۔ غالب اپنی فارسی شاعری پرجتناناز کریں بجا ہے لیکن فارسی ہمارے ملک کی زبان نہیں تھی اورخواص میں بھی فارسی کا ذوق مٹ رہاتھا۔ آج برصغیر پاک وہند میں غالب کا نام ان کی اردو شاعری اور اردوخطوط کی بدولت زندہ اور مشہور ہے۔
غالب نے بڑا پرآشوب زمانہ پایاتھا اور اس پرانہوں نے اپنے اردوخطوط میں جی کھول کر غم اور غصہ کااظہار کیاہے۔ یہاں تک توبات سمجھ میں آتی ہے۔ واقعی بڑی آزمائش اورمصیبت کا زمانہ تھا جس کو جہاں تک غالب کوستے کم تھا۔ غالب نے اس شعر میں جس احساس محرومی کا اظہارکیاہے وہ بہت صحیح ہے۔
نہ مرا دولت دنیا نہ مرا اجر جمیل
نہ چونمرود توانا نہ شکیبا چوغلیل
اس شعر میں اپنی حالت کی جوتصویرپیش کی ہے وہ درست ہے۔ البتہ ہم اتنا کہیں گے کہ غالب کوخلیل کی شکیبائی میسرنہ ہوسکی۔ یہ ان کے اپنے ذاتی مزاج کا قصورتھا۔ آخرمیر کو بھی توبڑا ہولناک زمانہ ملاتھا۔ مگر باوجود اس کے کہ زمانہ اورابنائے زمانہ پرکچھ ہجویں کہی ہیں جو جلی کٹی یا سب وشتم کا انداز لئے ہوئے ہیں۔ میر اپنے کردارکی سالمیت اوراپنی شخصیت کے وقار کو قائم رکھتے ہیں۔ غالب اپنے بلند آہنگ اورجلیل القدرپیغام کے باوجودنجی زندگ کی آزمائشوں کا ذکر کرتے ہوئے ضبط وتحمل وقاروتمکنت کوبرقرار نہیں رکھ پائے۔ یہ ان کی ذاتی کمزوری تھی۔
بہرحال غالب کوزمانہ کی گردش اور اس کی ناسازگاری کاجودکھ تھا وہ بشریت کا تقاضاتھا۔ اس پر ہم کوبازپرس کا کوئی حق نہیں۔ لیکن غالب کی اس شکایت کوہم مشکل سے تسلیم کرسکتے ہیں کہ ان کے زمانہ میں ان کی قدرنہیں ہوئی۔ اہل کمال کی اہل کمال ہی قدرکرسکتے ہیں۔ خواص کی قابلیت کوخواص ہی پرکھ سکتے ہیں۔ تاریخ کے کسی دور میں بھی اکثریت جوہرقابل کے حق میں ناشناس ہی رہی ہے۔ پھرجب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غالب کس قسم کے خارج المرکز جوہرقابل تھے تو عوام تو عوام تھے اگرخواص بھی ان کی قدر کا اندازہ کرنے سے قاصر رہ جاتے تو ان کو معاف کردیتے۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان خود ان کے زمانے میں غالب کی جتنی قدرومنزلت رہی وہ بہت کم لوگوں کونصیب ہوتی ہے۔ خواص کے ہرحلقہ میں ان کی محبت اور عزت کرتے تھے اور ان کے ساتھ خلوص ونیاز کا تعلق رکھتے تھے۔ ارباب علم وفضیلت میں مفتی صدرالدین آزردہ، مولانا امام بخش صہبائی، مولانا فضل حق خیرآبادی جیسی برگزیدہ ہستیاں غالب کے غیرمعمولی ذہن اوران کی اجتہادی قابلیت کے معترف تھیں اوران کے ساتھ شفقت اورمحبت برتتی تھیں۔ شیخ نصیرالدین عرف کالے خاں جیسے مانے ہوئے بزرگان رشد وہدایت کے ساھت غالب کے تعلقات بے تکلفانہ تھے۔ نواب ضیاء الدین خاں رخشان ونیرنواب الہی بخش خان معروف، نواب علاء الدین خاں علائی جیسے امیر اور رئیس غالب کے معتقدتھے۔ شاعری کا کھرا ذوق رکھنے والے غالب کے مرید تھے۔ جوان کے باقاعدہ شاگر دنہیں تھے۔ وہ بھی غالب کی صحبت کواپنے لئے فخر سمجھتے تھے اور شعوری طورپران سے اثرقبول کررہے تھے۔ نواب مصطفی خان شیفتہ و حسرتی رئیس جہاں گیرآباد جومومن کے شاگردتھے اورغلام علی وحشت ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ غالب کے ہم چشموں میں حکیم موہن خان موہن کا نام سب سے زیادہ اہم ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے مزاج داں تھے او رسچے دل سے ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے۔
اب ان لوگوں کی طرف آئیے جوغالب سے تلمذرکھتے تھے۔ غالب کوشاگردبنانے کاکوئی ارما ن نہیں تھا اوروہ شاگردوں کی کثرت کوفخر کی بات نہیں سمجھتے تھے لیکن جوکوئی ان کی شاگردی کا آرزو مندہوتاتھا یا اپنے کلام پر اصلاح چاہتا تھا اس کووہ کبھی مایوس نہیں کرتے تھے بلکہ نہایت فراخ دلی کے ساتھ اس کے اشعار پر اصلاح کردیتے تھے اورہمیشہ اس کے ساتھ خلوص اورشفقت کا برتاؤ کرتے تھے۔ جن رئیسوں اورامیروں کی طر ف اشارہ کیاگیاہے ان میں بیشترغالب کے شاگرد تھے اوربعض ایسے تھے جوغالب کو اپناکلام دکھاتے یا سناتے تھے اوران کے افکارو آرا سے بہ قدر طرف واستعداد مستقل اثرقبول کرکے اپنی شاعری میں جذب کرلیتے تھے۔
غالب کی بے نیاز طبیعت کے باوجود ان کے شاگردوں کی تعداد کثیر تھی اور سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی دہلی اورنواح دہلی میں ان کے جو شاگردان سے زیادہ قریب تھے ان میں نواب ضیاء الدین خان، نیردرخشاں اورنواب علاء الدین خان علائی کا ذکرکیاجاچکاہے۔ ان کے علاوہ الطاف حسین حالی مرزازین العابدین خاں عارف (جوغالب کی سالی کے بیٹے تھے اورجن کو غالب نے اپنا لڑکا بنالیاتھا) میرمہدی مجروح اورمنشی ہرگوپال تفتہ غالب کے بڑے محبوب شاگردتھے۔ اسی زمانہ میں ایک اورشاعر ہوا ہے جوعلی گڑھ کا رہنے والاتھا۔ خاندانی کائستھ تھا۔ بنواری لال نام تھا۔ شعلہ تخلص کرتا تھا۔ وکالت ذریعہ معاش تھی۔ حسرت موہانی نے شعلہ کوغالب کا شاگرد بتایاہے۔ اور ’’اردوئے معلی‘‘ کی کسی جلد میں ان کی غزلوں کا مختصر انتخاب بھی شائع کردیاہے۔ بنارس یونیورسٹی کے ڈاکٹرمہیش پرشاد نے غالب کے خطوط کا جونسخہ شائع کیاہے اس کے مقدمہ پر صاف طورکہا ہے کہ شعلہ غالب کے شاگردنہیں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ شعلہ منشی ہرگوپال تفتہ کے شاگرد تھے جوخودغالب کے عزیز ترین تلامذہ میں تھے۔ اس طرح شعلہ کا نسب شاعری غالب ہی سے ملتا ہے۔ جب ہم شیفتہ، حالی، مجروح کے رنگ سخن کوسامنے رکھتے ہوئے شعلہ کے کلام پرنظر ڈالتے ہیں تو وہ ہم کوذوق یا اسیرلکھنوی کے دبستان کے شاعرنہیں معلوم ہوتے بلکہ محسوس ہوتا ہے کہ زبان وبیان کے رکھ رکھاؤ کے ساتھ غالب کے کلام کے صالح عناصر سے وہ اپنی شاعری کے مزاج کی تربیت کرتے رہے ہیں۔
یہ بات ملحوظ رکھنے کے قابل ہے کہ غالب کے تلامذہ اورمعتقدین کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ رہی ہو اورانہوں نے کتنوں ہی کے اشعار پر اصلاح کیوں نہ کی ہو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کی پیچیدہ طرزفکر اور ان کے معمول سے ہٹے ہوئے اسلوب زبان وبیان کوجوں کا توں اختیارکرے اور جب وہ کسی کے کلام پر اصلاح دیتے تھے تو صاحب کلام کے مبلغ فکر اور معیاراظہار وابلاغ کو ہمیشہ مدنظر رکھتے تھے۔ غالب کو احساس تھا کہ انہوں نے اپنے لئے جو بدیع المثال انداز فکر اور رنگ سخن منتخب کیا اس کو وہ خود تونباہ لے گئے لیکن اگردوسروں نے اس سے مستفید ہونے کے بجائے اس کی اندھی تقلید کی تو اردوشاعری کے بدراہ ہوجانے کا خطرہ ہے۔ یہ امربھی قابل توجہ ہے کہ خودغالب کے زمانہ میں کسی نے ان کی تقلید نہیں کی۔ ان سے فیض یاب جتنے بھی ہوئے ہوں ان کی طرز اڑانے کی کوشش توبیسویں صدی کی پہلی چوتھائی کے اندرہوئی اوربعض ناعاقبت اندیش شاعروں کے سرمیں غالب بننے کا سوداسمایارہا لیکن یہ شعرا خود تو کوئی نمود حاصل نہ کرسکے البتہ غالب کی شاعری کوبدنام کرگئے۔ اکثرغزلیں اخبار وجرائد میں نظر سے گزرتی رہی ہیں جن کی نمایاں خصوصیات فارسی الفاظ وتراکیب اورغیر ضروری تشبیہات واستعارات کی بھرمار اورمعنی کی قلت یا معنی کااختلال ہے۔ تقریبا پچاس سال پہلے کچھ اشعارپڑھے یا سننے میں آتے تھے۔ دوتین اشعارنمونہ کے طورپرحاضر ہیں۔
سرشوریدہ پائے دست پیما شام ہجراں تھا
کبھی گھرتھا بیایاں میں کبھی گھر میں بیاباں تھا
ادادان فسوں کاری خماریں چشم قاتل ہے
زنخداں مکتب تعلیم سحر چاہ بابل سے
یہ میرٹھ کے ایک مشہور شاعر کے اشعار ہیں جواپنے زمانہ میں استادمانے جاتے تھے اور شاگردں کی خاصی تعداد رکھتے تھے۔
ایک اور شعر یاد آ گیا۔
پھر انا للہی بنے آماجگاہ اعتبار
دار کو پھر حسرت نظارہ منصور ہے
یہ بدایوں کے ایک صاحب کا شعر ہے جن کی غزلیں اخباروں میں چھپا کرتی تھیں۔
غالب کی طرف جولوگ مائل ہوئے اوران سے اصلاح لی یا ان سے اثرقبول کرتے رہے وہ بڑی سلیم اور صالح طبیعت اوربڑے مستقیم اورمحکم کردار کے لوگ تھے۔ ان میں تین یعنی شیفتہ حالی اور سرسید کا ذکرخصوصیت کے ساتھ کرنا ہے اس لئے کہ غالب کی فکر اوران کے لب اظہار کا جواثرہماری نظم ونثر میں اندرونی تموج کے طورپر اب تک جاری ہے وہ ایک سلسلہ ہے جس کی ابتدائی کڑیاں یہی تینوں شخصیتیں ہیں۔
شیفتہ مومن کے شاگردتھے۔ لیکن غالب سے ان کو دلی انس تھا اورہرحال میں وہ غالب کے رفیق اور ہمدرد تھے۔ مومن کے شاگرد رہتے ہوئے بھی وہ غالب سے مشورہ لیتے تھے اورمومن کے بعدتو وہ اپنا کلام باقاعدہ غالب کودکھانے لگے تھے۔ شیفتہ کی غزل سرائی میں نہ مومن کی چیستاں نگاری ہے اور نہ غالب کی فکری ژرف۔ ان کے بیان میں نہ مومن کی تعقید ہے نہ ان کا لفظی تضاد یا استحالہ اورنہ غالب کے اسلوب کی غرابت کی حد تک بڑھی ہوئی جدت۔ مگران کے اردو اور فارسی کلام کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں اساتذہ کا جوہران کے اپنے انفرادی فکری وفنی شعور کے ساتھ مل کر کام کررہاہے۔ ان کے اشعار میں ایک پرتامل سنجیدگی ہوتی ہے اوران کی زبان اورطرز اظہار میں ایک شائستگی اورلطافت کا احساس ہوتاہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اردوغزل کے مزاج میں فسادپیدا ہوچلا تھا۔ شاہ نصیراورذوق دہلی میں ناسخ اورانہیں سے مقابلہ اورمسابقہ کی دھن میں آتش اوران دونوں کے تلامذہ شاعری کو زبان اور صنائع بدایع کی بازی گری بنائے ہوئے تھے۔ ادھرامیرمینائی اوراسیرلکھنوی کے دوسرے شاگردوں اورداغ دہلوی اور ذوق کے پیروں کا عنفوان شبا ب تھا اوران کی آوازمیں لوگوں کومتوجہ کرنے لگی تھیں۔ ان کی سستی اورادنی قسم کی لذت پرستی اورخوش باشی کواردوشاعری میں قبول عام حاصل ہوناشروع ہوگیاتھا۔ غزل میں ابتذال کے آثار رونما ہوچلے تھے۔ ایسے میں شیفتہ حالی اورغالب اورمومن کے شاگردغزل کی فطری شرافت اور پاکیزگی اور اس میں احساس وفکر کی متانت کو قائم رکھ کرآنے والی نسل کے لئے مثال چھوڑ گئے۔ یہ معمولی اکتساب نہیں ہے۔ شیفتہ ایک اوراعتبار سے بھی تاریخی قدررکھتے ہیں۔ اردوشاعری کے جتنے اہم تذکرے ہیں لکھے جاچکے تھے جن میں بیشتر فارسی زبان میں ہیں۔ تذکرہ نگاری کا دورختم ہورہاتھا۔ اسی زمانہ میں شیفتہ کا تذکرہ ’’گلشن بے خار‘‘ سامنے آتاہے جوتنقیدی درک کا احساس دلاتاہے۔ ہیئت اورترتیب کے لحاظ سے یہ بھی تذکرہ ہے لیکن ہمیں اس میں کچھ یادگار جملے اورفقرے مل جاتے ہیں جوزیرنظر شاعر کے کلام کی انفرادی خصوصیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شیفتہ کی راتیں متوازن اور معقول ہوتی ہیں اور ان کا لب ولہجہ دقیع ہوتاہے۔ یہ پرتامل سنجیدگی اوریہ مفکرانہ شائستگی کا شیفتہ کااپنا مزاج ہے لیکن اس کی تہذیب میں مومن کی شاگردی اورغالب کی صحبت کوبھی بہت بڑا دخل ہے۔ بعد کی نسل نے شیفتہ کی ناقدانہ بصیرت سے بھی بہت کچھ پایاہے۔
حالی غالب کے نامورشاگرد تھے اورشیفتہ کے رفیق وجلیس۔ دونوں سے ان کوقرب اقرب حاصل تھا۔ حالی کئی حیثیتوں سے اردوادب کی تاریخ میں نیاموڑ ہیں۔ حالی کی یاد آتے ہی ہمارا ذہن بے ساختہ اردوشاعری کی اس صنف کی طرف منتقل ہوجاتاہے جواصطلاح میں نظم یا نظم جدید کہلاتی ہے اور جس کے بانی حالی اور آزاد دونوں ہیں مگرجو مقبول ومروج حالی ہی کے اکتسابات کی بدولت ہوئی۔ یاپھر ہمارا خیال اس حالی کی طرف جاتاہے جس نے اردومیں جدید طرز کی تنقید اور مغربی انداز کی سوانح نگاری کی نہ صرف بنیادڈالی بلکہ اس کوکچھ ایسا مقبول بنایاکہ آج تک ہم تنقید اور سوانح میں انہیں کے نکالے ہوئے راستہ پرمنزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے آئے ہیں۔ ’’مقدمہ شعروشاعری’‘ اردو میں پہلی ادبی دستاویز ہے جس میں شعر کی ماہیت اورغایت، شاعری کے اصول واوضاع اوراسکے اصناف واسالیب پرعالمانہ بحث کی گئ ہے اوران کے محاسن کا سنجیدگی اورشائستگی کے ساتھ جائزہ لیتے ہوئے بے اعتدالیوں اور بے عنوانیوں کے خطرات سے ہم کوآگاہ کیاگیاہے۔ ’’حیات سعدی‘‘ اور’’یادگار غالب‘‘ پہلے اقدامات ہیں جن میں اردومیں جدید سیرت نگاری، متوازن اورمتین سوانحی تنقید اور اکابر کے تخلیقی کارناموں پرجچے تلے اندازمیں انتقاد اور اشعار پرتجزیاتی اور تشریحی تبصرہ کا ایک نیا اورمستحکم معیارقائم ہوا حالی کا یہ ترکہ ہمارا بہت بڑا ادبی سرمایہ ہے جو تاحال ہمارے کام آرہاہے اور جس سے آئندہ نسلیں بھی کبھی بے نیاز نہیں ہوسکتیں۔ عام خیال یہ ہے کہ حالی اس نئے ماحول اوراس نئی فضا کی مخلوق تھے جومغربی اثرات کی وجہ سے ہماری تہذیب اورہمارے معاشرے کے ہرشعبہ میں پیدا ہوچلی تھی اور جس کوسرسید اور ان کے رفیقوں نے شعوری طورپرقبول کرکے بہت جلدعلی گڑھ تحریک کی منظم صورت دی۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس سے کوئی انکار نہیں کرسکتا۔ لیکن بات اتنی ہی نہیں ہے۔ ذراسوچئے اسی فضا کے اوائل میں مصحفی، جرات اور انشاگزرچکے تھے۔ ناسخ، آتش اور اسیر کو بھی یہی فضا نصیب ہوئی۔ ذوق بھی کسی دوسری فضا کے پروردہ نہیں تھے۔ امیراورداغ اسی فضا میں مانع ہوئے۔ آخر ان لوگوں کی شاعری میں نئی فضا کے آثار کیوں نہیں ملتے۔ ان لوگوں نے راہ فرارکیوں اختیار کی اور شاعری کی تفریح یا سستی قسم ک عیش کوی اور لذت پرستی بناکر اس میں پناہ کیو ں لی۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب صرف یہ ہے کہ نئے اسباب وموثرات اور میلانات وعوامل کوسمجھنے اور ان سے صحیح اثر قبول کرنے کے لئے بڑے حق شناس اور صالح ذہن اورہوش وتمیزکی ضرورت ہے۔ غالب نے ایسا ہی ذہن اور ایسی ہی استعداد پائی تھی اوران کے جتنے شاگرد اور معتقد اورجتنے ان کی عظمت فکرکے ماننے والے تھے سب حق شناس اورمعقول پسند تھے۔
ذکر حالی کا تھا۔ ہم حالی کی نظموں اورنثری کارناموں میں کچھ ایسا محورہتے ہیں کہ ان کی ایک اوراہم حیثیت کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ ان کی یہ حیثیت سرسید کے حیطہ اثرمیں آنے سے بہت پہلے قائم اورمسلم ہوچکی تھی اور یہ ان کی اولین حیثیت ہے۔ وہ پنے عصر کے نہ صرف اچھے غزل گوتھے بلکہ غزل کی جوممتاز خصوصیات انہوں نے ’’مقدمہ شعروشاعری‘‘ میں گنائی ہیں ان سب کو اپنی غزلوں میں برتابھی ہے اورجن بے اعتدالیوں کو ہمارے ذہن نشین کرایاہے ان سے خود سختی کے ساتھ اجتناب کیاہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالی نے غزل کو ڈوبنے سے بچاکر اس کی آبرو اورحرمت کی حفاظت کی۔ حسرت موہانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غزل کا احیاکیاہے۔ بہت صحیح ہے۔ لیکن اس احیامیں شاید دشواری ہوتی اگر حالی اور شیفتہ اس کوزندہ اور توانا نہ چھوڑگئے ہوتے۔ حالی کے اشعار ان تمام عناصر اور خصوصیات سے معمورہوتے ہیں جوتغزل کی فطرت میں داخل ہیں اور وہ اعتدال کے ساتھ ایسے اشارے بھی ہوتے ہیں جوتامل انگیز ہوتے ہیں مگر جو ان کومعمہ نہیں ہونے دیتے۔ ان کے اشعار سراسر حال ہوتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اول تو حالی کے مزاج میں سلامت روی تھی جوکبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی تھی۔ دوسرے ان کوغالب جیساصاحب ہوش ونظراستاد ملا جس کے ساتھ حالی کوپرخلوص ارادت تھی۔ اس نے ان کی تخلیقی بصیرت کو جلابخشی۔ ہم اس موقع پرحالی کے صرف چنداشعار کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتے ہیں۔
پردے بہت سے وصل میں بھی درمیاں رہے
شکوے وہ سب سنا کئے اورمہرباں رہے
دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام
کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے
ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب ترکہاں
اب ٹھہرتی ہے دیکھئے جاکر نظرکہاں
اک عمرچاہئے کہ گوارا ہو نیش عشق
رکھی ہے آج لذت زحم جگرکہاں
بے قراری تھی سب امیدملاقات کے ساتھ
اب وہ گلی سی درازی شب ہجراں میں نہیں
سخت مشکل ہے شیوہ تسلیم
ہم بھی آخر کو جی چرانے لگے
کس سے پیمان وفا باندھ رہی ہے بلبل
کل نہ پہچان سکے گی گل تر کی صورت
گھٹ گئیں کچھ تلخیاں ایام کی
بڑھ گئی ہے یا شکیبائی بہت
اگرپہلے سے یہ معلوم نہ ہوکہ حالی کوغالب سے تلمذ حاصل تھا اور اس دور کے تمام مشاہیرسخن کوجمع کیاجائے اور غزلیات حالی کوسامنے رکھ کرپوچھا جائے کہ حالی کس کے شاگرد ہوسکتے ہیں تواہل ذوق وبصیرت بے تامل کہہ دیں گے کہ غالب کے شاگرد تھے یا غالب کا اثران کے کلام میں نمایاں ہے اورپہچانا جاسکتاہے۔
تیسری شخصیت یعنی سرسید کے بارے میں کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں اس لئے کہ ان کی یاد میں اب تک دلوں میں جاگ رہی ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کومایوسی اورجمود کی مہلک فضا سے نکال کر سعی وعمل اورفلاح وترقی کے جس راستہ پر انہوں نے لگایا اس پر ہم آج تک گامزن ہیں اورتیزی کے ساتھ منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ سرسید خوداپنے زمانہ میں طرح طرح کے لعن طعن کانشانہ بنے رہے۔ مردہ ماضی کوسینے سے لگائے رہنے والے گروہ نے جواکثریت میں تھا ان کورسوا اورخوار کرنے میں کون سا طریقہ تھا جس کواٹھارکھاہو۔ ان کوکیاکیا نہیں کہا گیا۔ کافر، دہریہ، کرسٹان، یہ تھے وہ القاب جن سے ان کو نوازاگیاتھا اورآج بھی سرسید کی عظمت کوماننے والوں کے ساتھ ایسوں کی کمی نہیں جوسرسید کے تاریخی کردار سے تجاہل برت کران کوانگریزوں کا پرستار اورتاج برطانیہ کا ہوادار سمجھتے ہیں۔ ہمارا مقصد سرسید سے بحث کرنا نہیں ہے لیکن ان کے نازک پرخطر عہداوران کے ماحول کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ سرسید اگرچہ کوئی بڑے عالم فاضل نہیں تھے لیکن وہ بڑے بیدارمغزانسان تھے اورجو بیدارمغز انسان ہوتاہے وہ تھوڑے سے تھوڑے علم کوجید سے جیدعالم کے مقابلہ میں زیادہ مقبول اور مفید طورپرکام میں لاسکتاہے۔ اس لئے کہ اس کے اندر علم سے زیادہ شعور ہوتاہے۔ سرسید کی علمی استعداد جتنی بھی رہی ہو ان کا خاندان علم وحکمت میں ایک مقام رکھتاتھا اور اس زمانہ میں علم وحکمت کے معنی مسلمان خاندانوں میں مذہبی علم وحکمت کے تھے کیونکہ اس زمانہ میں سب سے زیادہ بحران مسلمانوں کی قسمت میں تھا اوروہ آٹھ سوبرس پرانی تہذیب جوتاریخ میں ہندومسلم تہذیب کے نام سے یاد کی جاتی ہے اورجوتمام اندرونی پیکار اور بیرونی طاقتوں کے جابرانہ اورجارحانہ دباؤ کے باوجود برصغیر ہندوپاک میں کسی طرح نیست و نابودنہیں ہوسکتی بہت بڑے خطرے میں تھی۔ اس تہذیب کی آخری ورثہ دارسلطنت مغلیہ تھی جور۱۸۵۷ء کی پہلی جذباتی جنگ عظیم سے پہلے ہی بالکل بے دست وپاہوکر رہ گئی تھی۔ غالب اپنی خاصی طویل عمر کی آخری دودہائیوں میں عبرت اوربصیرت کے ساتھ زمانہ کی اس گردش کاتماشہ دیکھ چکے تھے۔ سرسید ایک بالغ نظر نوجوان کی حیثیت سے اسی گردش سے گزررہے تھے۔ غالب اور سرسید دونوں کواس ثقافتی میراث کے زوال کا قلق تھا اور دونوں یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ میراث تباہی سے بچ جائے لیکن دونوں کویہ بھی احساس تھاکہ اب محض پرانے ذرائع اوروسائل سے کام نہیں چل سکتا۔ غالب اور سرسید دونوں شاہ ولی اللہ سے لے کر سید احمدشہید اورشاہ اسماعیل شہید تک ان تمام مصلحین ومجاہدین کے مساعی کے دل سے معترف تھے جنہوں نے مسلم علوم اوتہذیب ومعاشرت کوبچانے اور زندہ رکھنے کے لئے جانبازانہ اقدامات کئے، لیکن نہ تو غالب ان اصلاحی تحریکوں سے پوری طرح آسودہ تھے اور نہ سرسیدہی نے اس کو کافی و شافی سمجھا۔ سرسید نے متداولہ نصاب کے مطابق تعلیم پائی تھی لیکن وہ جاگتا ہوا ذہن لے پیدا ہوئے تھے۔ وہ ان تمام اصلاحی کوششوں کی قدر کرتے تھے جو دینی معاشرت کے اکابرین سے پیشتر کرچکے تھے لیکن وہ ۱۸۵۷ء کے بعد معتوب مسلمانوں کی ابترحالت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اوران کی یقین ہوگیا تھا کہ ترقی یافتہ انگریزقوم کی حمایت کے بغیرمسلمان ترقی نہیں کرسکتے۔ زندہ ماضی کے زندہ عناصر رکھتے ہوئے اگران کونئی زندگی کے نئے مطالبات ومیلانات اورنئے اقداروعوامل کے ساتھ ہم آہنگ نہ بنایاگیا اور مشرقی تہذیب میں مغربی علوم وفنون کی لائی ہوئی توانائیوں سے نئی روح نہ پھونکی گئی تو نہ وہ تہذیب باقی رہے گی اورنہ اس تہذیب کے ورثہ دار زندہ رہیں گے۔ یہ صرف حکمت عملی نہیں تھی بلکہ دور تک سوچاسمجھا ہوانقطہ نظر تھا جس کوبرصغیر کی دوسری قومیتوں نے بہت پہلے سوچ سمجھ کر اس پرعمل شروع کردیا تھا اورترقی کرنے لگے تھے۔ سرسید کی فکروبصیرت کا جائزہ لیتے ہوئے ان تما م اسباب وموثرات کونظر میں رکھنا ہے لیکن یہ حقیقت بھی کم اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ غالب کے حق شناس اورصلاح پسند اور پیش رس مزاج کے قائل اوران کے خیالات اورمیلانات سے گہرے اثرات قبول کرچکے تھے۔ پھرسرسید کی مرتب کی ہوئی ’’آئین اکبری‘‘ پر غالب نے تفریظ کے طورپر جو مثنوی لکھی ہے اور اس میں نیک نیتی اور شفقت کے ساتھ جوجچی تلی رائے دی ہے اور جس کا مطالعہ آج بھی ہمارے لئے بصیرت افروز ہوگا اس نے سرسید کی نظر اور ان کی فکر کویقینا نئی روشنی دی اور ان کووقت کے متقضا اورزندگی کے نئے مطالبے کا ازسرنو جائزہ لینے پرآمادہ کرنے میں موثر اوراہم حصہ لیا۔ مثنوی سے چندمنتحب اشعاریہاں درج کئے جارہے ہیں جن سے غالب کی دیدہ وری اور درست اندیشی کا اندازہ ہوتاہے۔ اورجوآج بھی ہم کوفکر اور گفتار کا سلیقہ سکھاسکتے ہیں۔ سب سے پہلے ’’آئین اکبری‘‘ کے سلسلے میں سرسید کی محنت کی داد دیتے ہوئے ان کو متنبہ کرتے ہیں۔
دیدہ بینا آمد وباز وقو ی
کہنگی پوشیدہ تشریف نوی
دیں کہ در تصحیح آئیں رائے اوست
ننگ و عار ہمت والائے اوست
اس کے بعد وہ ان ایجادات اورنئے اسباب ترقی اور معاشرتی اور آئینی اصلاحات کی طرف توجہ دلاتے ہیں جوانگریز نے دراصل تواپنے استعماری اور استحصالی مقاصد و مصالح کے لئے اوراقتدار حکومت کومضبوط ومستحکم بنانے کے لئے مہیاکئے مگرجوآج تک ہمارے کام آرہے ہیں۔ ان کا اعتراف نہ کرناان کے خیال میں بے ایمانی کے مترادف تھا۔ ’’صاحبان انگلستان‘‘ کے شیوہ نداز ہمارے ’’دیرکہن‘‘ کے لئے اپنے مفا دکے بہانے کیا کچھ کرگئے، اس سلسلے میں مثنوی مذکورکے کچھ اشعارملاحظہ ہوں۔
داد ودانش رابہم پیوستہ اند
ہندرا صد گونہ آتیں بستہ اند
آتشے کزسنگ بیرون آورند
ایں ہنر منداں زخس چوں آورند
تاجہ افسوں خواندہ اندایناں برآب
دودکشتی راہمی راند درآب
نغمہ ہائے بے خمہ از سازآورند
حرف چون طائر بہ پرواز آورند
کاروبار مردم ہشیار بیں
در برآئیں صد نو آتیں کاربیں
پیش ایں آئیں کہ دارد روزگار
گزشتہ آیتن دگر تقویم پار
مگریہ سب کچھ توسرسید کوچونکاکر ہوشیارکرنے اور’’مردہ پروری‘‘ سے محتاط رہنے کے لئے کہا گیا ہے۔ غالب سرسید کو ایک ہونہار نوجوان سمجھتے تھے۔ وہ ان کی ’’ہمت والا‘‘ کا صحیح اندازہ رکھتے تھے۔ اس ’’سراپافرہ ہنگ‘‘ سے ان کو بڑی امیدیں تھیں۔ سرسید ان کوبہت عزیزتھے۔ وہ مثنوی کودل سے نکلی ہوئی دعاؤں پر ختم کرتے ہیں۔
درجہاں سید پرستی دین تست
از ثنابگزر دعاآئین تست
ایں سراپا فرہ فرہنگ را
سید احمدخاں عارف جنگ را
ہرچہ خواہد از خدا موجود باد
پیش کارش طالع مسعودباد
سرسید طبیعتا نہ شاعرتھے نہ انشاپرداز، اگرچہ وہ آہی تخلص رکھتے تھے اور اوائل عمر میں انہوں نے شعرکہے جو اس وقت سامنے نہیں ہیں۔ وہ ایک مفکرتھے اور ان کاایک نظام فکر تھا جس کی بنیاد افادیت اورعملیت پر تھی۔ ان کا نصب العین ایک ایسے معاشرہ کوبچاکر اس کونئی زندگی اورتوانائی سے معمورکرتا تھا جوایک عظیم تاریخی ورثہ تھا اور جو اس وقت چارموج میں گھرا ہواتھا اورڈوب جانے کے خطرہ میں تھا۔ وہ اپنے نصب العین میں بہت بڑی حد تک کامیاب رہے اس معاشرہ کا ایک لازمی جزو اردوادب یعنی اردونظم ونثر بھی تھا۔ اس لئے ان کوسنجیدگی کے ساتھ اردوزبان اوراس کے ادب کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ وہ متقدمین کے تمام تخلیقی کارناموں کی قدرکرتے ہوئے شدت کے ساتھ محسوس کررہے تھے کہ اردوزبان اور اس کے ادب کے جملہ اصناف واسالیب کوبدلنے اور ان کو نئی قدروں سے بھرپور کرنے کے لئے سخت اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ وہ زمانہ کے نئے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوکر ہمارے معاشرہ کو زندہ اور صحت مندرکھنے میں مددگارثابت ہوسکیں۔
سرسید اردوزبان ادب کی تاریخ میں تین اعتبارات سے اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو اس ناقابل تردید حقیقت کویاد رکھناچاہئے کہ سرسید اس جدید اردوادب کے جداعلیٰ ہیں جس کی بنیادسائنٹیفک سوسائٹی مسلم ایجوکیشنل کانفرنس اورایم اے اوکالج علی گڑھ کے ساتھ پڑی۔ سرسید کی مقناطیسی شخصیت نے بہت جلد اپنے گرد ایسے نوجوانوں کاحلقہ پیدا کرلیا جو معقول پسند مزاج رکھتے تھے اورسرسید کے منصوبوں کو سمجھ سکتے تھے اور ان کی ہم نوائی کی جرأت کرسکتے تھے۔ پھرسرسید کی سربراہی میں ان کے رفیقوں نے اردوادب کے احیا اور اس کی بقا وترقی کے لئے جوزندہ جاویداقدامات کئے وہ ہماے ادب کی تاریخ کا ایک روشن باب بن چکے ہیں۔
خودسرسید نے اردوکے نثری ادب میں ایک ایسی صنف کااضافہ کیا جس کا وجود ہماری زبان میں نہیں تھا۔ یہ صنف مختصرمضمون یا انشائیہ ہے۔ سرسید یہ صنف انگریزی زبان سے لائے تھے جس میں وہ بیکن سے اسٹیل، ایڈیسن اور گولڈ سمتھ تک اچھی طرح بالغ ہوچکی تھی۔ ان انشائیوں میں کچھ جھلک غالب کے خطوط کی بھی مل جاتی ہے جومراسلات کی شکل میں وقتی حالات یا زندگی اور شاعری کے رموزونکات پرہلکے پھلکے مضامین بھی ہوتے تھے۔
سرسید کے لئے بڑی مشکل یہ تھی کہ ان کے سامنے اردونثر کا کوئی ایسا اسلوب نہیں تھا جس کو وہ اختیارکرتے اور جواس قابل ہوتاکہ ان کے تمام فکری نظام اور عملی منصوبوں کوسنجیدگی اورسادگی کے ساتھ کثیر سے کثیرتعداد تک پہنچاتا اور جس کو سب مانوس اورسہل پائے۔ ’’سب رس‘‘ سے نوطرز مرصع اور نوطرز مرصع سے باغ وبہار اورفسانہ عجائب تک نثرکاکوئی اسلوب سرسید کے مقاصد کے لئے موزوں نہیں تھا۔ ایک غالب کے خطوط کی نثرایسی تھی جو سنجیدہ تھی اور شگفتہ بھی اور ہرقسم کے معانی اور مفاہیم کے اظہار پر قادرتھی۔ سرسید نے اسی کو اختیار کیا اور اس میں انگریزی انشائیہ کے اسالیب کی کچھ خصوصیات کوداخل کرکے اس کوبالکل اپنا اسلوب بنالیا جو ان کے پیغام کوصاف اور شفاف زبان میں عوام تک پہنچاسکتاتھا۔ مگرسرسید کی نثراس ادبی کشش سے یک قلم عاری ہے جو’’عودہندی‘‘ اور’’اردوئے معلی‘‘ کی ممتازخصوصیت ہے۔
حالی نے شاید سرسید کی نثر میں اس کمی کومحسوس کرلیا۔ وہ غالب کے محبوب شاگردوں میں تھے اورغالب سے بہت قریب رہ کر ان کی شاعری اوران کی اردو نثر دونوں کے مزاج کوسمجھے ہوئے تھے اور دونوں کی عظمت کے راز سے بہ خوبی آگاہ تھے۔ وہ اپنے اسلوب میں وہ ’’سادگی وپرکاری‘‘ تونہ پیدا کرسکے جوغالب کے اردو خطوط کی جان ہے لیکن ان کی سادہ اوربے تکلف نثر میں ایک متین اور متوازن ادبی کیفیت ہوتی ہے۔ حالی کا نثری اسلوب ایک جامعیت بھی اپنے اندررکھتا ہے اورایسا ہوتا ہے کہ اس میں تنقیدیں، سوانح انشائیے سبھی کچھ لکھے جاسکتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالی کا اسلوب غالب اور سرسید کے اسالیب کے درمیان ایک مفاہمت ہے۔ اگرحالی نہ ہوتے تو جدیداردو نثر کے ادب بننے میں نہ جانے کتناعرصہ لگتا۔
نثری روایات عصرجدید یا نئی نسل کی نثر کوکس طرح او رکس حد تک متاثر کرتی ہیں؟ یہ بات آسانی سے ہماری سمجھ میں آجاتی ہے لیکن کسی زبان کی شاعری بالخصوص بربطی یاغنائی (Lyric) شاعری میں زبان کی نثرکی تہذیب و تحسین میں کس حد تک شریک رہتی ہے۔ اس کا اندازہ مشکل سے ہوتاہے۔ اس لئے کہ نثر پر شاعری کا جواثرہوتا ہے وہ بہت خفی اورلطیف ہوتاہے۔ یہ خود اپنی جگہ ایک موضوع ہے جومفصل بحث چاہتاہے۔ بہرحال غالب کی نثراورنظم دونوں نے جدید اردونثر کے اسالیب کے ارتقا میں بڑا حصہ لیا ہے۔ ان کے اردوخطوط نے ہماری ’’نثر کوسادگی اور بے ساختگی کے ساتھ ساتھ چستی اورطراری دی اور ان کی شاعر نے نثر میں فکری تعمق اورخیالی نزاکت، حکیمانہ فرزانگی اورجمالیاتی لطافت پیداکی۔ حالی اور شبلی سے پریم چنداورچکبست اورنیاز فتح پوری اوران کے ہم نواؤں تک کے اسالیب کونظرمیں رکھئے۔ زمانہ (کانپور) ادیب (الہ آباد) صلائے عام مخزن، تمدن، نقاد سے ہمایوں، نیرنگ خیال نگار اور اس دور کے دوسرے اردوجرائد میں نثر کے اسالیب میں جوتنوعات پائے جاتے ہیں ان کا غور سے مطالعہ کیجئے توبیسویں صدی سے غالب تک اردونثر ایک تاریخی سلسلہ ہے جس میں کہیں کوئی خلایاعدم ارتباط محسوس نہیں ہوتا۔ بیسویں صدی کی پہلی دودہائیوں تک ایک خاص طرزنگارش ہماری نثری ادب میں بہت مقبول رہی جس کو مبہم طور پر ادب لطیف کہا جاتارہا اور جس کو خواہ مخواہ کچھ لوگوں نے ایک علیحدہ ادبی صنف سمجھا حالانکہ وہ محض ایک اسلوبی میلان تھا۔ اس میلان کے سلسلے میں ایک نئی ادبی صنف ضرور وجود میں آئی جو شعر منثور (Prose Poen) کہلاتی اور کچھ عرصہ تک رائج رہی۔ یہ میلان جدید رومانیت یعنی عہد وکٹوریہ کے اواخر کا ترکہ تھا اور برطانوی اقتدار کے استحکام کے ساتھ برصغیر کے فکر واظہار اوراس کی تہذیب ومعاشرت پراثراندازہونے لگا۔ شعرمنثور کی نئی صنف براہ راست اسکروائلڈ اور ٹیگور کے مطالعہ کا نتیجہ تھی اورمغرب ہی سے آئی تھی۔ یہ سب باہری اثرات تھے۔ لیکن اگرغالب کی گمبھیر شاعری اور اس کی بلیغ اسلوبی کیفیتیں ہمارے تخلیقی شعور میں جذب نہ ہوچکی ہوتیں توان اثرات کے اظہار کے لئے زبان اوراسلوب تراشنا دشوارہوتا۔
لیکن کسی دوریا کسی دبستان یاکسی فرد واحد کی شاعری کا اثرآئندہ دور پرکیا پڑا؟ ہم کوبعدکے شاعروں کے کلام ہی سے اس کا صحیح اندازہ ہوسکتا ہے۔ حالی تک غالب کا اثرزیربحث آچکاہے۔ اب بیسویں صدی کے آغاز سے تیس سال کی اردوشاری پرنظرڈال لی جائے۔ اس تیس سال نے اردوشاعری کوفکر واحساس کی نئی نزاکتوں اور بلاغتوں اور زبان واسلوب کی توانائیوں اوراثرفرینیوں سے جس طرح مالامال کیا اس کی نظر اس سے پہلے نہیں ملتی۔ جدید شاعری کی ان تمام نت نئی صوری و معنوی کیفیات میں غالب کی فکروگفتا رکے آثار وعلامات بہت واضح نظر آتے ہیں۔
سب سے پہلے جواردوشعرااس سلسلے میں یادآتے ہیں وہ مولانا وحشت کلکتوی، علامہ اقبال حسرت موہانی اورشادعظیم آبادی ہیں۔ مولانا رضا علی وحشت معمولی شخصیت کے آدمی نہیں تھے۔ وہ عالم متجراور فاصل اجل تھے۔ اردوفارسی اور عربی زبانوں اوران کے ادبیات پر وہ ماہرانہ اور مبصرانہ عبور رکھتے تھے۔ انگریزی زبان پربھی ان کو اتنی قدرت حاصل تھی کہ اس میں تنقیدی مضامین لکھا کرتے تھے جومختلف انگریزی اخبارورسائل میں چھپ سکتے ہیں۔ اردوزبان میں بھی ان کی ادبی تنقیدیں اپنے زمانے میں اختراعات کا درجہ رکھتی تھیں۔ یہ تنقیدیں زیادہ تر اس دور کے سب سے زیادہ مقتد ر اردوجریدہ؟ لاہور میں شائع ہوتی رہیں۔ وہ اسلامیہ کالج کلکتہ میں شعبہ فارسی واردو کے صدریامعلم اول تھے۔ ان کی یہ حیثیات مسلم تھیں اورا کی بنا پر نہ صرف صوبہ بنگال میں بلکہ برکوچک کے دوسرے صوبوں میں بھی ان کی عزت اور تعظیم کی جاتی تھی لیکن ہمارے برکوچک کی تہذیبی تاریخ میں وحشت کلکتوی کا مستقل اورپائدار اعتبار کچھ اورہے۔ وہ اردو اورفارسی دونوں زبانوں میں نہ صرف اچھے شعر کہتے تھے بلکہ دونوں زبانوں کی شاعری میں اپنا منفرد اور ممتازمقام رکھتے تھے۔ اس سے پہلے بیسویں صدی کے اوائل کے بعض ماہواررسائل کاذکرآچکاہے جنہوں نے سرسید ک رسالہ تہذیب الاخلاق کے بعداردوادب کونئی شاہراہ پرلگانے کے سلسلے میں بڑا کام کیاہے۔ ان رسائل میں ’’مخزن‘‘ لاہور مرکزی حیثیت کامالک ہے۔ دوسرے رسائل اپنے تنوعات کے باوجود اساسی اعتبار سے ’’مخزن‘‘ کے ہم خیال ہم نظر اور ہم آہنگ تھے۔ اس لئے اگر ۱۹۰۵ء سے ۱۹۲۰ء تک کے ادبی اورثقافتی اکتسابات کوکسی دبستان کے نام سے موسوم کیاجائے تواس کو ’’دبستان مخزن‘‘ کہنا بہت مناسب ہوگا۔ وحشت کلکتوی اسی دبستان کے تربیت یافتہ تھے اور اپے ہم دبستانوں میں بڑی قدراورعزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ اس زمانہ میں کسی مانے ہوئے استادسے تلمذضروری تھا ورنہ توآغاز شاعر بے استاداکہا جاتا تھا۔ وحشت کوبھی اپنے لئے استادمنتخب کرناپڑا۔ یہ ابوالقاسم شمس تھے جو عبدالغفور خاں نساخ کے بیٹے اور داغ دہلوی کے شاگردتھے لیکن شمس کا جلدہی انتقال ہوگیا اورپھر وحشت نے کسی دوسرے سے اصلاح نہیں لی۔ وحشت شاعری کی خدادادصلاحیت لے کرپیدا ہوئے تھے اور انہوں نے خود’’کسب فن‘‘ کے لئے بڑا ریاض کیا۔ ان کا ذہن دوسروں سے بہترین اثرات قبول کرکے جذب کرلینے کی قابلیت رکھتا تھا۔ چنانچہ ان کے کلام میں میر، مومن اور داغ سبھی کے کچھ نہ کچھ آثار مل جاتے ہیں لیکن خود ان کوغالب کی پیروی پرناز تھا اوروہ اس کااعلان بھی کرتے تھے۔ ایک فارسی شعر میں کہتے ہیں،
سخن آموخت غالب از نظیری وحشت از غالب
چراغے راکہ دودے ہست در سرزود درگیرد
فارسی میں بھی وحشت نے انہیں اساتذہ کے کلام کواپنے لئے نمونہ بنایا جن کی پیروی غالب کرگئے تھے یعنی سعدی، فغانی، حزیں، عرفی، نظیری، ظہوری، صائب وغیرہ۔
ان کا تخلص بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ غالب کے ساتھ ظاہری اورباطنی ہرنوع کا قرب اقرب محسوس کرناچاہتے تھے۔ غالب کے ایک نہایت عزیز اور سریرآوردہ شاگردسید غلام علی خاں کاتخلص وحشت تھا۔ سب سے پہلے حالی نے وحشت کلکتوی کے پہلے مجموعہ کلام ’’دیوان وحشت‘‘ (مطبوعہ ۱۹۱۰ء) پررائے دیتے ہوئے اس بات کا خیال دلایا۔ وحشت کے کلام میں غالب کی متانت فکر اور نزاکت احساس کے ساتھ غالب کے اسلوب کی ندرت اورطرفگی اعتدال اور ہمواری کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ ان کے زمانہ کے اکابر میں کون ہے جس نے ان کی شاعری کی ان خصوصیات کوتسلیم نہ کیا ہو۔ بزرگوں میں حالی اور شبلی نے فراخ دلی کے ساتھ وحشت کے کلام میں غالب اور مومن کے انداز فکر اور طرزاظہار کی تعریف کی ہے۔ وحشت کے ان معاصرین میں جوکہ کم وبیش ان کے ہم عمرتھے اورجن سے ان کے تعلقات مخلصانہ تھے سرعبدالقادر ڈاکٹر اقبال اور مولانا ظفر علی خان تاریخ سازہستیاں تھیں۔ یہ سب لوگ صدق دل سے وحشت کی شاعری کے قدرشناس تھے اورسب نے جی کھول کر ان کے کلام کی داددی ہے۔
وحشت کا ذکرکچھ طویل ہوگیا۔ اس کی ضرورت تھی۔ ہم وحشت کوبھول چکے ہیں اوران کی یاد کے بغیر کم سے کم شاعری میں غالب کی نکتہ سرائی کے سطحی یا زیریں ارتعاشات کا تاحال جوسلسلہ جاری ہے اس میں ایک خلاپیدا ہوجائے گا۔
اقبال کے نظام فکر اوراندازبیان میں ’’گفتہ غالب‘‘ کے نشانات وعلامات اتنے واضح ہیں کہ ان کی مزید توضیح تحصیل حاصل ہوگی۔ اقبال کائناتی بصیرت اور آفاقی شعور لے کرپیدا ہوئے تھے۔ وہ خودفطرتا ایک مفکرتھے اورمفکرین کی عالمی برادری میں ان کا ایک مقام ہے۔ ان کامطالعہ بھی نہایت وسیع اورجامع تھا۔ مشرق اور مغرب کے قدیم اورجدید تمام ارباب فکر وفن کے کارناموں نے تامل کے ساتھ پڑھا تھا اور ان سے اپنے دل ودماغ کی تہذیب کی تھی۔ وہ کائنات کی ماہیئت فطرت انسانی کے رموز واسراراورانسانی زندگی کے مسائل ومعاملات کوسمجھے ہوئے تھے اوران پر اپنے سوچے ہوئے خیالات رکھتے تھے۔ ان کو احساس تھاکہ ان کو نئے زمانہ کونیاپیغام دیناہے۔
یہ عجیب اتفاق ہے کہ وحشت کلکتوی کی طرح اقبال بھی داغ دہلوی ہی کے شاگرد ہوئے اوران کے بتدائی کلام میں داغ کے اثرات صاف نمایاں ہیں۔ داغ کی وفات پر انہو ں نے جونظم کہی ہے اس سے ظاہرہوتا ہے کہ ان کے دل میں استاد کی کتنی عزت اور محبت تھی۔ وہ زندگی کاایک حکیمانہ نظریہ رکھتے تھے جس کی ترکیب میں دنیا کے عظیم ترین دماغوں کے عناصر وعوامل داخل تھے لیکن جو بہرحال ان کااپنا نطریہ تھا۔ ان کااپنے عہد کے لئے ایک پیغام تھا۔ جواسلاف واخلاف کے تاثرات وتاملات کا نہایت صحیح اور خوش آہنگ امتزاج ہوتے ہوئے بھی اپنی انفرادی توانائی کاحامل تھا۔ ایسا صاحب فکر ونظر شاعرظاہر ہے داغ کی منزل پر ٹھہرنہیں سکتاتھا۔ پھر غالب کی طرف ان کے ذہن کامڑجانا اور پھرغالب ہی کے فکری اوراسلوبی اجتہاد افرینی سے اپنے تخلیقی شعور کوبرابرتقویت پہنچاتے رہنا قدرتی بات تھی۔ اقبال کو اپنے برصغیر میں اگرکوئی مغربی مفکروں اور شاعروں کاہمسرنظر آتاتھا توہ وغالب تھے۔ انہو ں نے غالب کی خدمت میں اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ’’گلشن دیمر‘‘ کے آسودہ خاک گوئٹے کو غالب کا ’’ہمنوا‘‘ کہا ہے اور گوئٹے مغرب کے ان حکیم شاعروں میں سے تھا جن کی آواز کے ارتعاشات اقبال کی شاعری میں جابجا محسوس طورپرملتے ہیں۔ اقبال کی شاعری میں غالب کی توانائی اورنیرنگی زبان وبیان کا اثرکتناجاری وساری اور کس قدر مربوط اور مستقل ہے۔ اس کوسمجھنے کے لئے زیادہ تجزیہ یاتشریح کی ضرورت نہیں ’’شکوہ‘‘ اور ’’جواب شکوہ‘‘ اور ’’شمع وشاعر‘‘ سے ’’خضرراہ‘‘ اور ’’طلوع اسلام‘‘ اور پھر ’’بال جبریل‘‘ اور’’ضرب کلیم‘‘ تک کیانظموں میں کیا غزلوں میں اقبال کاکلام قدم قدم پرغالب ہی کی یاددلاتاہے اورہم کہہ سکتے ہیں کہ ’’شاعرفردا‘‘ کی نوا میں ’’گلشن ناافریدہ‘‘ کی عندلیب کی نغمہ سنجی کچھ اس طرح پیوست ہے کہ اس کوکسی ترکیب سے الگ نہیں کیاجاسکتا۔
اقبال ہی کے سلسلے میں ان کے ہم عصر شاعرچکبست کاذکر کردینا بے محل نہ ہوگا۔ سماجی اورسیاسی مسائل میں دونوں کے نقطہ نظر میں فرق تھا مگردونوں اسباب و حالات کے ایک ہی سلسلہ اورزمانہ کی ایک ہی فضا کی مخلوق تھے وہ اوران کے رفیق بش نرائن اورابرآتش۔ یاشنکرنسیم اورمیرانیس کے کافی حد تک متاثر تھے لیکن چکبست کے کلام کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فکر غالب اور بیان غالب سے وہ کچھ کم مستفیض نہیں ہوئے۔ انہوں نے نہایت معقول اور متوازن ذہن پایا تھا۔ ان کی شاعری اوران کی تنقید میں جوٹھہراؤ اوراعتدال ملتاہے وہ اس بات کا ثبوت کہ ان کا ادبی شعور حالی سے براہ راست متاثرتھا۔
یہ فقرہ بہت عام ہوگیاہے کہ حسرت نے اردوغزل کا احیاکیا۔ لیکن جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ غزل کی متانت اور اس کی پاک دامنی کوحالی محفوظ کرگئے تھے۔ حسرت نے حالی کی روایت کو فروغ دیا اور غزل کے ناموس کوبچاکر اس میں نئی جان ڈالی اورنئی توانائیاں پیدا کیں۔ حسرت سے اردوغزل میں نہضت کا دور شروع ہوتاہے۔ میں ایک سے زائد بارحسرت کو انتخابی شاعر (Electic Poet) کہہ چکا ہوں۔ میرسے مصحفی اور مصحفی سے غالب تک ہربڑے شاعر کا رنگ ان کی شاعری میں سلیقہ کے ساتھ سمویاہوا ملتا ہے۔ وہ خود امیراللہ تسلیم کے شاگرد تھے۔ اس طرح ان کی شاعری کاشجرہ مومن تک پہنچتا ہے اور اس سے انکار نہیں کیاجاسکتا ہے کہ مومن اوران کے نامور تلامذہ مثلا شیفتہ اصغرعلی خاں نسیم دہلوی مولا بخش قلق وغیرہ کا اندازسخن حسرت کے کلام میں جابجاملتا ہے۔ ان کی غزلوں میں ایسے حصہ کی بھی کمی نہیں جن کا تعلق معاملہ بندی اورادابندی سے ہے۔ ایسے اشعار میں مصحفی جرأت اورمومن کا رنگ جھلکتا نظر آتاہے لیکن تاثر کی پرگداز سنجیدگی الفاظ کے انتخاب کی ندرت ترکیب الفاظ کی تازہ کاری کا جہاں تک تعلق ہے اس امر کی شہادت بھی کثرت کے ساتھ ملتی ہے کہ حسرت کی شاعری میں غالب کی روح بھی کام کررہی ہے۔ حسرت کے ذہن کو غالب سے فطری قریب تھا۔ ان کے مزاج کوغالب کی جری اوربے باک طبیعت کے ساتھ خلقی یگانت تھی جوشعوری بھی تھی اور غیرشعوری بھی۔ اس کی ایک ظاہر علامت تو یہ ہے کہ اپنی طالب علمی کے زمانہ میں جب ایم اے اوکالج علی گڑھ میں انہوں نے اردو کی ادبی انجمن قائم کی تو اس کا نام ’’اردوئے معلی‘‘ رکھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ اردوکی ادبی انجمن کانام آج تک یہی ہے۔ پھرحسرت نے اپنے مشہور اردوجریدہ کابھی نام ’’اردوئے معلی‘‘ رکھا۔
حسرت اپنی شاعری سے باہر ایک جامع الحیثیات شخص تھے۔ سماجی اقتصادی زندگی برصغیر کی آزادی اورسامراج سے بغاوت کے بارے میں ان کا ایک مستحکم نظریہ تھا اوروہ ایک واضح اور مستقیم عملی نصاب کے علمبردار تھے جس پر سب سے پہلے وہ خودکاربندرہے۔ شاعری میں بھی ان کا ذوق جانبازی اور حق کے لئے سرکٹادینے کاولولہ اپنے کورموز واستعارات کے پردے میں ظاہر کرتارہتا ہے لیکن قضا وقدر تخلیق یافلسفہ کی زبان میں ’’وجودیات‘‘ ’’علمیات‘ اورغائیات جیسے مباحث پراگران کے کچھ خیالات رہے بھی ہوں توان کی بابت حسرت کی شاعری سے ہم کوئی قیاس نہیں کرسکتے۔ حسرت خالص عشق کے شاعر تھے اور عشقیہ شاعری میں حسرت کا فکری آہنگ اور اسلوبی ہنجارمومن اورغالب ہی کی عشقیہ شاعری کی یادتازہ کرتا رہتاہے۔
شادعظیم آبادی کاسلسلہ تلمذ خواجہ میر درد سے ملتا ہے۔ وہ میردرد کے حلقہ کے دوسرے معروف شعرا میر ضیا خواجہ میراثر میرمحمدی بیدار سے بھی متاثر ہیں۔ میرمصحفی اور آتش کی آوازوں کی گونج بھی ان کی غزلوں میں محسوس ہوتی ہے۔ ان کی زبان میں جوسلاست اور روانی ہوتی ہے اورالفاظ کی دردست میں جوقرینہ ہوتا ہے اس میں انیس کا بھی حصہ ہے لیکن میں حیث الکل ان کے اشعار میں ایک پرگداز تامل ایک تہہ رس تفکر کا احساس ہوتاہے جو ذہن جدید کی ایک عام شناخت ہے اورجس کا رشتہ غالب ہی سے ملتاہے۔
یہ امرقابل لحاظ ہے کہ اردومیں شاعری کی وہ صنف جواصطلانظم کہلاتی ہے نہ صرف وجودمیں آچکی تھی بلکہ اچھی طرح بالغ ہوگئی تھی۔ اقبال چکبست سرورجہاں آبادی وغیرہ کی کوششوں سے اردونظم میں وہ تاثراتی گمبھیرپن وہ فکری تعمق وہ اسلوبی نکھار آگیاتھا جو ان سے پہلے نہیں تھا۔ شوق قدوائی جواسیرلکھنوی کے شاگرد تھے اورایک قدیم دبستان کی آخری یادگارتھے۔ اپنی مشہور مثنوی اور نظموں بالخصوص ’’عالم خیال‘‘ اور’’بہار‘‘ کے ذریعہ ہم کو نئی رومانیت سے آشناکرچکے تھے۔ اس دور کے مقتدر ادبی رسائل کی ورق گردانی کیجئے جن کی سربراہی میں ’’مخزن‘‘ کورہا تھاتوآپ کوبہت سے شاعر ایسے ملیں گے جنہوں نے جدید اردونظم کی تربیت اورتہذیب میں نمایاں حصہ لیاہے مگرجن کو آج ہم بھولے بیٹھے ہیں ان میں سب سے زیادہ بلند بانگ مولاناظفر علی خان تھے جونہایت نوفکر آتش نوااور زودگوشاعر ہونے کے علاوہ بڑے شعلہ زبان اور شعلہ نگار مقرر اورصحافی بھی تھے۔ حکومت برطانیہ حسرت موہانی کی طرح ان کوبھی بہت خطرناک آدمی سمجھتی تھی اوران کو ’’پیدائشی باغی‘‘ کہتی تھی۔ یہ تمام لکھنے والے جہاں تک نئے انداز احساس اور نئے میلان فکروتخیل کا تعلق ہے مغربی تعلیم اورمغربی تصورات ونظریات کے ممنون تھے لیکن زبان وبیان کی نئی ترا وخراش اور نئے اوضاع واسالیب کی اختراع میں غالب ہی سے سہارا مل رہا تھا۔ غالب کے بعداردوشاعری کی نئی نسل کی رہنمائی اقبال نے کی۔
نظم کی روزافزوں مقبولیت کے باوجود ابھی تک غزل ہی اردوشاعر کی نمائندگی کررہی تھی اورمشاعروں میں اورعوام کے درمیان غزل ہی پسند کی جاتی تھی اور غزل ہی کی مانگ تھی۔ غزل کی یہ سحرآفرینی آج تک اپناکام کررہی ہے۔
یہ بیسویں صدی کی پہلی دودہائیوں تک کاحال ہے۔ یوروپ کی پہلی جنگ عظیم کا طوفان فروہوچکاتھا۔ محکوم قومیں اورنوآبادیاں امیدلگائے ہوئے تھیں کہ جن آئینی رعایات وحقوق کاسرکار برطانیہ وعدہ کرتی آئی ہے وہ اب ہم کومل جائیں گے۔ ہمارابرصغیر بھی بڑی امنگوں کے ساتھ انتظارکررہا تھا اورہم کوملاکیا رولٹ ایکٹ کا بہائمی قانون اورجلیانوالہ باغ (امرتسر) کابھیانک واقعہ۔ اسی کے ساتھ ترکی کے ساتھ برطانیہ کی قیادت میں مغربی طاقتوں کے جابرانہ اورجارحانہ سلوک نے مسلمانوں کواوربھی برافروختہ کردیا۔ پھر دیکھتے دیکھتے ہماری ذہنی فضابدل گئی۔ ہمارے سارے التباسات دورہوگئے اورہم کویقین ہوگیا کہ ہم کواپنی سیاسی آزادی اقتصادی فلاح اور معاشرتی بہبود کے لئے نیا لائحہ عمل مرتب کرناہے۔ ۲۱۔ ۱۹۲۰ء تک ایک دورختم ہوچکا تھا اور ایک دوسرے دورکی ابتدا ہوچکی تھی۔
شعراور ادب کی دنیا میں اقبال کی نظمیں ’خضرراہ‘‘ اور ’’طلوع اسلام‘‘ ایک سنگ میل کاحکم رکھتی ہیں۔ دونوں ہمارے اندریہ احساس پیدا کرتی ہیں کہ زمانہ ایک نیاموڑاختیارکرچکا ہے اوراب نئے راستہ پرگامزن ہے۔
انہیں دنوں کی بات ہے کہ دیوان غالب کا ’’نسخہ حمیدیہ‘‘ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری کے ہاتھوں میں مرتب ہوا جس میں غالب پر ان کا معرکۃ الآرا اور عہد آفریں مضمون مقدمہ کے طورپرشامل تھا۔ یہ مضمون بعدکو’’محاسن کلام غالب‘‘ کے نام سے ایک کتاب کی شکل میں بھی چھپا۔ اربا ب ذوق وفکر میں اس کی دھوم مچ گئی اورغالب پسندجھوم اٹھے۔ بجنوری شاعربھی تھے۔ ان کی شاعری کا عنوان خود ان کے زمانہ میں توممتازاورمنفردتھاہی مگرآج بھی وہ اپنی فکری کائنات اوراپنی اسلوبی فضا کی بنا پر سب سے الگ ہیں اورپہچانے جاسکتے ہیں۔ یہ کہنا کافی نہ ہوگا کہ غالب کے متبعین میں وہ سب سے زیادہ غالب سے قریب تھے۔ وہ غالب میں محو ہوگئے تھے اورغالب کی روح ان میں سرایت کرگئی تھی۔ انہوں نے تمام مغربی حکما شعرا اور دوسرے فنکاروں کابھی ڈوب کرمطالعہ کیاتھا اورسب کا جوہراپنے اندر جذب کرلیاتھا۔ اگر تجزیہ کیا جائے توسب کے اثرات کا پتہ چل جاتاہے۔ لیکن اگریہ پہلے سے کوئی نہ جانتا ہو کہ وہ مغربی علوم وفنون سے بہرہ ور تھے تو وہ دوسرے غالب معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجسمہ ساز اور اس کے تخلیقی عمل پر ایک مختصرسی نظم لکھی تھی جو’’نقیب‘‘ (بدایوں) کے ۱۹۲۱ء کے شمارے میں شائع ہوئی۔ اس کا ایک شعرپیش کیاجاتا ہے جس سے ان کے پورے فکری مزاج کااندازہ کیاجاسکتاہے۔
سنگ خدا نے کی نگاہ فکر کے جوں شعاع ماہ
خانہ دل میں پائی راہ جلوہ کناں خیال تھا
یہی بجنوری کی نثرکابھی اندازتھا یعنی ان کا نثری اسلوب بھی ہم کو غالب کی شاعری ہی کی دھن میں ملتاہے۔ ان کی جوانی کی موت اردوادب کے لئے بہت بڑاخسارہ تھی۔ صرف چند منظومات اور ’’محاسن کلام غالب‘‘ سمیت کچھ نثری تخلیقات بجنوری سے یادگار ہیں جوایک مختصر مجموعہ کی شکل میں شائع ہوگئے ہیں۔
۱۹۲۱ءسے ہمارے تصورات نظریات اورعملی مقاصد واقدامات میں ایک نئی منزل شروع ہوتی ہے اور شعروادب میں بھی ایک نئی نسل ابھرتی ہے۔ قبل اس کے کہ اس نئی نسل کاجائزہ لیاجائے ایک ایسے بے نفس وبے ریاشاعرکوبھی یادکرلیاجائے جس نے انیسویں صدی کی آخری دہائی میں شعرکہنا شروع کیالیکن جس کا چرچاپہلی جنگ عظیم کے بعد زیادہ ہوا اور وہ بھی خواص کے حلقہ تک محدود رہا۔ دل شاہجہان پوری ایک سربرآوردہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اورایک خوش فکر اور خوش بیاں شاعرتھے، امیرمینائی کے شاگرد تھے اورجلیل مانک پوری کے بعداپنے استاد کے جانشین قرارپائے۔ اپنے زمانہ کے ہردبستان کے سربرآوردہ شاعروں اور نثرنگاروں سے اپنی سخن وری اورسخن شناسی کی تحریری داد پاچکے ہیں۔ دل شاہجہان پوری کے کلام میں امیرمینائی کی شستہ ورفتہ زبان کا مزہ ہے مگروہ ابتذال اورعامیانہ پن یا کسی قسم کی عریانی کسی شعر میں نہیں آنے دیتے۔ ان کے یہاں میر کی خستگی اور گداختگی ہے۔ کہیں کہیں مومن کاانداز بھی پایاجاتاہے لیکن جو خصوصیات ہم کوسب سے زیادہ ان کی طرف کھینچتی ہیں وہ الام زندگی اورالام عشق کا پرتفکراحساس الفاظ کی ترتیب اور فارسی ترکیبوں کا سلیقہ اور اعتدال کے ساتھ استعمال ہے جن سے ان کے اشعار میں بلاغت کے ساتھ ایک مدہم نغمگی پیدا ہوتی ہے اور یہ ساری خصوصیات غالب ہی کا ترکہ ہیں۔
انہیں ایام میں اردوکے دوماہوار رسالے ’’ہمایوں‘‘ (لاہور) اور’’نگار‘‘ (بھوپال) شائع ہونے شروع ہوئے جنہوں نے دبستان مخزن کی رائج کی ہوئی پیش رفت روایت کوفروغ دیااور اس کونئے ادبی اور تہذیبی میلانات وخیالات سے معمورکرکے مزیدتوانائی بخشی۔
صفی لکھنوی عزیز لکھنوی ثاقب لکھنوی فانی بدایونی اور یاس عظیم آبادی کی شاعری نے اسی دور میں شہرت پائی۔ صفی کی غزلوں میں جہاں اپنے عصر کی فضا میں پھیلے ہوئے دوسرے اثرات کا احساس ہوتا ہے وہاں تاثر اور اظہار دونوں میں غالب کے خاموش اثرکی بھی علامتیں واضح ہیں۔ صفی لکھنوی کی نظموں میں بھی یہ خصوصیات موجودہیں۔
اس گروہ کے شاعروں میں عزیزلکھنوی اس لئے خصوصیت کے ساتھ قابل ذکرہیں کہ انہوں نے اعلان مبارزت یانبردطلبی کے انداز میں غالب کے رنگ میں شعرکہنا شروع کیا اور بہت سی غزلیں غالب ہی کی زمینوں میں کہہ ڈالیں لیکن ان کی غزلوں میں نہ وہ گمبھیرسوزوگداز ہے جوغالب کا اصلی جوہر ہے اورنہ زبان وبیان میں وہ ندرت و نغمگی ہی ہے جو غالب کی امتیازی شان ہے۔ سوزوگداز کی جگہ عزیز کے کلام میں مرثیت آگئ ہے اوران کے بیان میں بجائے بلاغت الفاظ کی بے کیف فراوانی کا احساس ہوتاہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ غالب کا حکیمانہ تغزل توایک طرح عزیزکی طبیعت کوسرے سے تغزل ہی سے کوئی لگاؤنہیں تھا۔ وہ یاتوقصیدہ کے شاعر ہوسکتے تھے یا دبیر جیسے مرثیہ نگار۔ چنانچہ ’’گلکدہ‘‘ سے زیادہ ’’صحیفہ ولا‘‘ میں وہ اپنے اصلی مزاج میں نظرآتے ہیں اور اس صحیفہ میں ایک منقبت نگارکی حیثیت سے انہوں نے غالب کی جوبھی کچھ آبرورکھ لی ہے۔ عزیزلکھنوی نے بہرصورت ایک خدمت توانجام دی ہے۔ انہوں نے دبستان لکھنو کی غزل کواس ابتذال اورسوقیت اوررکاکت اورعامیانہ پن سے بچالیا جوامانت اور فصاحت امیرمینائی اورداغ وغیرہ کے اندھادھند تتبع کی وجہ سے ساری غزل سرائی کو بری طرح آلودہ اورناپاک بناچکی تھی۔
ثاقب لکھنوی کوغالب سے فطری نسبت تھی۔ ان کی غزلیں کبھی تاثر اورتفکر کے جھکاؤ کبھی الفاظ اورلفظی تراکیب کی ساخت مگرزیادہ تردونوں اعتبارات سے رہ رہ ہمارے ذہن کو غالب ہی کی طرف منتقل کرتی ہیں۔ وہ کیف سے زیادہ آگاہی کیف کے شاعر ہیں۔ ان کے اشعار میں ایک پراشتیاق تامل اورایک مستفسرانہ آروزومندی کی ہلکی اورہموار دھڑکنیں محسوس ہوتی ہیں۔ ان کے بعض اشعار میں دبستان لکھنؤ کی آوازکی لہریں بھی ملتی ہیں لیکن ایسے اشعار میں بھی اسلوب بیان کچھ غالب ہی کے انداز کاہوتاہے۔ بعدکی نسل کے شاعروں نے غیرشعوری طورثاقب لکھنوی سے بہت کچھ سیکھا ہے۔
فانی بدایونی ذاع کے شاگرد اوردبستان داغ کے دوسرے شاعروں سے متاثرتھے۔ ان کے بالکل ابتدائی کلام میں اصلی سوزوگداز نہیں ہے بلکہ وہ ماتمی دھن ہے جس کو مکتبہ عزیزکے سخنور سوزوگداز کے عنوان سے پیش کررہے تھے۔ کہیں کہیں زبان وبیان مں ی وہ تصنع یا آوردبھی ہے جوخالص لکھنؤ کی پیداوار ہے۔ لیکن فانی فکری مزاج رکھتے تھے اوروہ مغربی علم وادب سے بھی آشناتھے۔ یوروپ کے متشائم حکما اورشعرا سے وہ خاص طورپر اثر قبول کرچکے تھے۔ ایسا دھن محض داغ جیسے شاعروں سے آسودہ نہیں رہ سکتا۔ اس لئے فانی کا بہت جلد غالب کی سمت مائل ہوجاناقدرتی امرتھا۔ فانی غزل کے شاعرہوتے ہوئے بھی ایک نظام فکررکھتے تھے جس کوغالب کے فلسفہ حیات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ غالب موت کا راگ نہیں گاتے۔ فانی کے نظریہ کے مطابق ساری تخلیق کی علت عشق ہے اور عشق اور غم ہمزاد ہیں اورغم کا لازمی انجام موت ہے۔ غالب کی فکریات میں اس مرگ اندیشی اور فناکیشی کوکوئی دخل نہیں لیکن اول توفانی نے غزل میں ایک مسلسل اور منظم پیغام دینا غالب ہی سے سیکھا۔ دوسرے اس پیغام کے اظہار و ابلاغ کے لئے انہوں نے جس زبان اورانداز بیان کواختیارکیا وہ غالب ہی کی وراثت ہے۔ کہیں کہیں مومن کی نزاکتیں بھی آجاتی ہیں۔ لیکن الفاظ اوران کی دردبست خصوصافارسی ترکیبوں سے فانی اپنی شاعری میں جو بلاغت اورمعنوی حجم بیساختہ پیدا کرلیتے ہیں وہ غالب ہی سے حاصل کی ہوئی سعات ہے۔ فانی ایک عرصہ تک نوجوانوں بالخصوص طلبا کے دل ودماغ پرچھائے رہے۔ ان نوجوانوں میں بعض تو انہیں کی دھن میں کھوئے رہے لیکن کچھ تعداد ایسے شاعروں کی بھی ہے جنہوں نے اس دھن سے اپنے لئے ایک الگ دھن نکال لی اور بعدمیں خوداپنا اپناممتاز مقام پیداکرلیا۔
یاس عظیم آبادی اپنی شاعری اورشخصیت دونوں کے اعتبار سے کچھ عجیب قسم کے آدمی تھے۔ اردوغزل کی فضا میں انہوں نے جوآوازبلند کی وہ اپنی نوعیت کی نئی آوازتھی۔ ان کی شاعری کی روح رواں محض جذباتیت (Emotionalism) نہیں ہے بلکہ وہ میلان ہے جس کو جدید اصطلاح میں ارادیت (Volunitarism) یا فعالیت کہناچاہئے۔ وہ خالص آرزو کے شاعرنہیں ہیں۔ وہ ذوق سعی اورحوصلہ پیکارکے شاعرہیں۔ ان کی شاعری کے خمیر میں جوعناصر بنیادی ہیں وہ میر، آتش، غالب اورانیس کے اثرات ہیں۔ ان میں سب سے قوی اور مستقل اثرغالب کا ہے۔ ان کے کلام میں آلام عشق اور آلام زندگی کی جو کسک محسوس ہوتی ہے وہ میرکاپرتو ہے۔ مردانگی اور بانکپن آتش کا ہے۔ رزمیت اوراسلوب بیان کی ہمواری اورروانی میں کچھ جھلک انیس کی ہے لیکن یاس کی شاعری کو جس خصوصیت نے اس قابل بنایا کہ وہ ہردور کے نوجوان ذہن میں نیاتموج پیداکرتی رہے وہ غالب کا تفکر ہرحال میں زندگی کے تناقصات و مشکلات پرفتح پانے کے لئے دعوت نبرداپنے نفس اورکائنات کے ساتھ مجاہدہ کی تلقین کی ہے۔ پھران کے اسلوب میں جونت نئی کیفیتیں ہوتی ہیں ان پرغالب ہی کی مہرہوتی ہے۔ غالب ہی کی طرح ان کی ترکیبوں میں تازگی اور عبارت میں طرفگی ہوتی ہے۔ غالب ہی کی طرح وہ اپنے استعمال سے پرانے الفاظ میں نئی جان اورنئی شان پیدا کردیتے ہیں۔ مختصریہ کہ غالب اوراقبال کے بعداگرکسی کی غزل میں زندگی کاولولہ مقادمت کی تاب اور پیش قدمی کی توانائی ملتی ہے تو وہ یاس ہی کی غزل ہے۔ وہ اپنی جگہ بھی ایک قوت تھے اور دوسروں کوبھی متاثر کرنے کی شدید قوت رکھتے تھے لیکن ان سے نئی پودنے بہت دیرمیں اثرقبول کرناشروع کیا اوروہ بھی کچھ غیرشعوری طور پر۔ اس کے ذمہ دار خودیاس تھے۔ اول تواپنے کلام کی اشاعت کے معاملہ میں وہ بہت بے نیاز تھے۔ اس زمانہ کے اردوماہنامے کبھی کبھی ان سے غزلیں حاصل کرلینے میں کامیاب ہوجاتے تھے۔ ’’ہمایوں‘‘ (لاہور) سب سے زیادہ خوش نصیب تھا۔ کچھ عرصہ تک ماہ بہ ماہ وہ یاس کی غزلیں شائع کرتا رہا۔ اس دورمیں یاس کی سب سے زیادہ قدرلاہور والوں نے ہی کی۔ دوسری بات جس نے یاس کونقصان پہنچایا وہ ان کے مزاج کی چڑچڑاہٹ اورجھلاہٹ ہے جوآخر میں کلبیت کی حد تک بڑھ گئی۔ عزیزلکھنوی کے گروہ کے ساتھ جھگڑوں نے ان کے غیظ وغضب کوایسا بھڑکایا کہ وہ غالب پرغصہ اتارنے لگے اوراپنا ڈھنڈورا آپ پیٹنے لگے اوربالآخر یاس سے یگانہ چنگیزی بن گئے۔ اس نے ان کو سنجیدہ اور باذوق طبقہ میں بہت سبک بنادیا۔ ’’آیات وجدانی‘‘ ان کی تخلیقات شعری میں شاہ کار ہے لیکن ان کے لکھے ہوئے محاصرات رکاکت اور چھچھورے پن کی عبرت ناک مثالیں ہیں۔
جس دہائی کاہم ذکر کررہے ہیں ہمارے شعور اورہمارے ذوق عمل دونوں کے لئے نشاط ووجدانی اورنئی سرگرمیوں کا زمانہ تھا۔ اردوادب میں بھی یہ دہائی نئی برکتیں لائی اورتنوع اوروسعت دونوں کے اعتبار سے اس میں نئی بالیدگیاں پیدا کیں۔ ’’ہمایوں‘‘ اور ’’نگار‘‘ کے ساتھ نہ جانے کتنے علمی وادبی جرائد واخبار اسی زمانے میں نکلناشروع ہوئے جن میں سے اکثرشعلہ مستعجل ثابت ہوئے۔ ایسے جرائد میں حکیم احمدشجاع مرحوم کا ماہواررسالہ ’’ہزارداستان‘‘ خصوصیت کے ساتھ یاد رکھنے کے لائق ہے جوصرف افسانے مسلسل ناول ڈرامے اورمنظومات شائع کرتا تھا۔ ’’ہزارداستان‘‘ صوری اور معنوی نفاستوں کامعیاری نمونہ تھا۔ حکیم احمدشجاع اوران کا ’’ہزارداستان‘‘ دونوں اس تہذیب کے ممتازنمائندے تھے جس کواگراردوتہذیب کہا جائے تو مناسب نہیں ہوگا اورجس کی پرداخت میں غالب کاکردار بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ان تینوں رسالوں نے کئی نوجوان شاعروں اور ادیبوں کی نئی صلاحیتوں اوران کی تخلیقی کوششوں سے ہم کومتعارف کیا۔ ان میں جوش ملیح آبادی، لطیف الدین احمد، اکبر آبادی، مخمور اکبرآبادی، خلیقی دہلوی، حفیظ جالندھری، سیدعلی عابد، اخترشیرانی جیسی شخصیتیں شامل ہیں۔ ان سب کے احساسات وافکار اوراسالیب اقبال کے توسط سے یا براہ راست غالب کی اثر آفرینیوں کی علامتیں لئے ہوئے ہیں۔
۲۱۔ ۱۹۲۰ءکی بات ہے جب شبیرحسن خاں جوش ملیح آبادی کا نام پہلی بار ہم نے سنا۔ ان کے رشحات کاپہلا مجموعہ ’’روح ادب‘‘ چھپ کرہمارے سامنے آیا۔ یہ شعر منثور کی قسم کے چندپاروں، کچھ غزلوں اور کچھ متفرق اشعار پرمشتمل تھا اوراس زمانہ کے اعتبار اورجوش کے اپنے معیار کے مطابق بڑے اہتمام سے مجلد اور تصویروں سے مزین شائع کیاگیاتھا۔ یہ جوش کی جوانی کا وہ دور تھا جب ان کے لئے ریل کاسفر جنگ کا میدان ہوتا تھا ااور وہ ہراسٹیشن پرتازہ زخم کاری دل پرکھاتے رہتے تھے۔ جوش کی شہرت بائرن کی شہرت سے ملتی جلتی ہے جس سے وہ خود بھی کئی اعتبارات سے مماثلت رکھتے ہیں۔ بائرن نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ ایک صبح وہ سوکراٹھا اوراپنے کو مشہورپایا۔ جوش اپنی تین نظموں سے یکایک مشہور ہوگئے۔ یہ تینوں نظمیں ’’نگاہ اور دل کا تصادم‘‘ ’’جنگل کی شہزادی‘‘ اور ’’ناسزاجوای‘‘ نگاری‘‘ ’’نگار‘‘ ۱۹۲۲ء میں شائع ہوئیں۔ اس کے بعد مختلف رسالوں میں ’’سہاگن بیوہ‘‘ ’’مہترانی‘‘ اورکئی دوسری چھوٹی چھوٹی نظمیں شائع ہوتی رہیں۔ جوش کا اصلی مزاج انہیں نظموں میں پایاجاتاہے۔ وہ رومانی طبیعت رکھتے تھے۔ تفکر اورتعمق کا توکوئی شائبہ ان کی شاعری میں نہیں ملتا۔ لیکن یہ اندازہ ضرور ہوجاتا ہے کہ تاثر اور تخیل کی صلاحیتیں ان کے سریع اور شدید ہیں۔ وہ فطرتا عشق ورومان کے آدمی ہیں۔ انداز سے معلوم ہوتاہے کہ ان کی شاعری انگریز کے رومانی شعرا سے مواد حاصل کرتی رہی ہے۔ عالم فطرت کے خارجی مظاہرے ومناظر کے بیان میں ورڈسورتھ سے سطحی طورپر متاثرہیں۔ لیکن بائرن اوربعد کے رومانی شعرا کی احتساسیت ان کے وہاں زیادہ ہے۔ پھران کی رومانی شاعری بھی کبھی کبھی ترکانہ تیورلئے ہوئے ہوتی ہے اور ان کی نظموں میں قصیدہ کا سا لفظی شکوہ اورلہجہ کی سطوت کااحساس ہوتاہے۔ یہ شایدفقیر محمدخان گویا کے وارث اورعزیزلکھنوی کے شاگردہونے کالازمی نتیجہ ہے۔ انیس کی رزمیت اورزبان کی روانی بھی جوش کے کلام کی ایک خصوصیت ہے۔ لیکن ان کی شاعری میں جوانحرافی میلان ہے وہ اقبال کے واسطے سے غالب کے خانوادہ فکر وفن سے مربوط ہے۔ اقبال سے اثرقبول کرنے کا توشاید جوش اعتراف نہ کریں مگرغالب سے بے نیازی کادعویٰ وہ کریں بھی توکوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ وہ عزیز لکھنوی کے شاگردرہ چکے ہیں اورعزیز لکھنوی ارادہ اوراہتمام کے ساتھ غالب کی تقلید کرتے تھے۔ جوش الفاظ کی ترتیب اور فارسی ترکیبوں سے اپنی نظموں میں جوتوانائی اورتاثیرپیدا کردیتے ہیں اس سے غالب ہی کی طرف دھیان جاتاہے۔ اس باپ میں وہ اپنے استاد سے زیادہ سلیقہ ہنرمندی کا ثبوت دیتے ہیں۔ انحرافی میلان اور جرأت اظہار جوش کی شاعری کی ناقابل انکار خصوصیات ہیں۔ شاعری کی نئی نسل کوان کی یہی خصوصیات سب سے بڑا عطیہ ہیں اوریہ دونوں غالب اور اقبال ہی سے وابستہ خصوصیات ہیں۔ مگرایسا معلوم ہوتا ہے کہ جوش انحراف اور بیباکی کو مقصودبالذات سمجھتے ہیں۔ ۱۹۳۵ء کے بعدوہ انقلاب کے شاعر سمجھے جانے لگے۔ لیکن وہ انقلاب اورترقی کے تاریخی تصوراور نوامیس سے ناواقف ہیں۔ اورآزادی کوکچھ شخصی قسم کے چیزسمجھتے ہیں۔ اس لئے ان کا نعرہ انقلا ب محض بغاوت کا خروش ہوکررہ جاتاہے۔
اسی زمانے میں دوخالص غزل سراؤں کی شہرت ہونے لگی۔ یہ اصغر گونڈوی اورجگرمرادآبادی ہیں۔ دونوں دوبالکل مختلف انواع کے شاعرہیں۔
اصغرگونڈوی حسرت موہانی کی طرح امیراللہ تسلیم کے شاگردتھے اورنسیم دہلوی کے واسطے سے ان کا سلسلہ مومن تک پہنچتاہے۔ زبان اوربیان میں اصغر کی شاعری کہیں کہیں نسیم اور تسیم کی یاد دلاتی ہے۔ لیکن فارسی الفاظ اور فارسی ترکیبوں سے جولطافت اوردلآویزی وہ اپنے کلام میں پیدا کردیتے ہیں اس سے پایاجاتاہے کہ ان کی طبیعت بیان غالب کی طرف زیادہ راغب ہے۔ اس بیان میں انہوں نے کچھ اپنے رنگ کی پاکیزگیاں پیدا کرلی ہیں جن سے وہ پہچانے جاسکتے ہیں۔ جہاں تک فکری کائنات کاتعلق ہے اصغر کوغالب سے کچھ زیادہ مناسبت نہیں معلوم ہوتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اصغر فکروتعقل کے شاعر نہیں ہیں وجدان وتاثیر کے شاعر ہیں توزیادہ صحیح ہوگا۔ وہ ’’مسائل تصف‘‘ کے شاعر ضرور ہیں مگریہ مسائل غالب کے مسائل سے مختلف اورممتازہیں اوران کے اپنے تخیل اوراپنی بصیرت کی تخلیق ہیں۔ وہ نمودجلوہ بیرنگ کے شاعر ہیں اوران کی ساری شاعری پرایک سدیمی (Nebulous) فضاچھائی رہتی ہے۔ اصغر ان شخصیتوں میں سے ہیں جوخوداپنی جگہ بڑی قوتوں کی مالک ہوتی ہیں لیکن دوسروں پر اپنا اثر کم چھوڑجاتی ہیں۔ اصغرکے مقام کی انفرادیت سب نے تسلیم کیالیکن کسی نے نہ ان کی تقلید کی، نہ کرسکتا تھا۔
جگرمرادآبادی کی غزل سرائی کا رشتہ داغ سے ملتاہے۔ جگرکی غزل داغ کی غزل کاایک بالیدہ زیادہ مہذب اوراثرجدید کے تقاضے کے مطابق جدید روپ ہے۔ جگرکی شاعری کا موضوع عشق ہے اوروہ بھی جسمانی یا حسی عشق۔ مگر انہوں نے اس حسی عشق میں بڑی نزہتیں اورپاکیزگیاں پیدا کی ہیں۔ وہ عشق کی نازک کیفیتوں اورپرخطر ساعتوں کا تیزاحساس رکھتے ہیں۔ وہ حسن کے مزاج دل اور ادا شناس ہیں۔ ان کے اشعار میں محبوب کے سراپا کے ایسے نکتے، ایسے خطوط اورایس پیچ وخم ہماری آنکھوں کے سامنے آجاتے ہیں جوہم کو نئی یافت معلوم ہوتے ہیں۔ عاشق کی حالت اورمحبوب کے برتاؤ وصل کی کیفیت اور ہجر کی کلفت کوبیان کرنے کا ان کوملکہ حاصل ہے۔ ان کی شاعری روایتی زبان میں ادابندی اور معاملہ بندی کی شاعری کہی جاسکتی ہے لیکن اس باب میں وہ داغ سے زیادہ مومن سے قریب ہیں۔ ان کے اس عنوان کے اشعار کاآگہانہ ہوتے ہوئے رکاکت اور عریانی سے پاک ہوتے ہیں اوران میں شرافت اورمعصومیت کااحساس ہوتاہے۔ کہیں کہیں غالب کی سادگی وپرکاری بھی پائی جاتی ہے لیکن جگرکی جو صفت ہمارے لئے موجودہ بحث کے سلسلے میں سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے وہ الفاظ کی بندش اور فقروں کی تراش ہے اور ان کااچانک استعمال ہے۔ جگرکی زبان اورطرزبیان پرغالب کا ہلکامگرمستقل پرتو ہے۔ ان کی شاعری کی یہی خوبی نوجوانوں کو بے اختیار اپنی طرف کھینچتی رہی۔ جگرکی یہ کشش اب تک کام کررہی ہے۔ کچھ شاعروں کوتوجگر کی پیروی نے واقعی شاعر بنادیا لیکن ایسوں کا شمار زیادہ ہے جوجگرکی تقلید میں بہک کربدراہ ہوگئے اورکہیں کے نہ رہے۔
۱۹۳۵ء میں برصغیر ہند وپاک کی سیاسی، اقتصادی، معاشرتی تاریخ نئی منزل کی جستجومیں، پھرایک نیاراستہ اختیارکرتی ہے۔ اسی سال برطانوی سامراج نے برصغیر میں کمیونسٹ پارٹی کوایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے قانونی طور پرتسلیم کیا اور اس کواعلانیہ تبلیغ وتنظیم کی اجازت دی۔ فرقہ وارانہ عطیہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۲۵ء کی شکل میں اس سال ملااورجداگانہ انتخاب کے ذریعہ اسمبلی اور مرکزمیں اراکین چنے گئے اورپہلی مرتبہ ملکیوں کوحکومت سنبھالنے کا موع دیاگیا۔ ایک سال بعد انجمن ترقی پسند مصنفین قائم ہوئی اور ادب میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ سرسید کی تحریک کے بعدبرصغیر میں یہ دوسری منظم ادبی تحریک تھی۔ اس نے ہماری فکراور تخلیقی توانائی کونئی سمتوں سے آشناکیا۔ اردو میں بہت سے نئے میلانات اسی تحریک کے سلسلے میں داخل ہوئے اور ہیئت اوراسلوب کے کچھ جدید تنوعات اردواد ب میں اسی تحریک کے فروعات ہیں جن کی تشریح وتفصیل کا یہ موقع نہیں لیکن غالب اورغالب کے بعداقبال آزادی فراخ دلی اوربیباکی کے ساتھ نئے تصورات اورنظریات کوچاہے وہ کہیں سے آئے ہوں قبول کرکے اپنے فکری مزاج میں جذب کرلینے اوراسے بھی زیادہ آزادی اوربیباکی کے ساتھ ان کو معرض گفتار میں لے آنے کی جرأت ہمارے اندر نہ پیدا کرگئے ہوتے تو ان باہر سے آئے ہوئے نئے تصورات ونظریات سے مانوس ہونے اورقرینہ کے ساتھ ان کا اظہار کرنے میں ہم کودقت اورزحمت ہوتی۔
غالب کی غیرفانی شخصیت اوران کے اثرکی ہمیشگی کا قیاس اس سے کیاجاسکتا ہے کہ وہ روح عصر نہیں روح دہر لے کرپیدا ہوئے تھے۔ غالب کے تصور کے ساتھ ورڈسورتھ، گوئٹے، شیلی اور وٹمین کی یادکچھ فطری ایتلاف کے طورپر آجاتی ہے۔ انہیں عالمی مفکر شاعروں کی طرح غالب کا تخلیقی نفس انفرادی اور مقامی سے گزر کر آفاقی اور آفاقی سے گزرکرکائناتی پہنائی اورگہرائی رکھتا تھا۔ دنیا کی کسی ترقی یافتہ اورمہذب زبان میں اس زبان کے کرداراورناموس کوقائم رکھتے ہوئے غالب کے کلام کومنتقل کردیاجائے تووہ اس زبان کے لئے نیاانکشاف ہوگا۔
اب تک اردو ادب بالخصوص اردوشاعری پرغالب کے اثرکاجائزہ لیتے ہوئے کسی قدر تجزیاتی تفصیل سے کام لیاگیا تھا جس کی ضرورت تھی۔ ہم اپنے دور اور اس کے پیچیدہ سے پیچیدہ ترہوتے جانے والے اسباب وعوامل میں کچھ اس طرح مبتلا اورمحوہیں کہ زیادہ پیشتر کی نسلوں کے اقتباسات تودرکنار اپنے دور سے ایک نسل پہلے کے بھی کارناموں کی تاریخی ترتیب وتسلسل کے ساتھ وئی درک نہیں رکھتے لیکن اب ہم ایسے دورمیں پہنچ گئے جس کا امتدادچالس سال سے کم ہے جس کی ابتدابرصغیر کی کمیونسٹ پاری کے قیام اور ترقی پسند تحریک کے آغاز سے ہوتی ہے اور جواپنا دور ہے ہم اس دور اوراس کے اکابرسعی وپیکار اورمشاہیر فکروفن سے اتنا قریب ہیں کہ ان کے فضائل ومساعی کا تفصیل وتجزیہ کے ساتھ جائزہ نہ اس وقت ممکن ہے اورنہ اس کی چنداں ضرورت ہے۔
گزشتہ چاردہائیوں کی مدت میں غالب ہمارے دل ودماغ میں اس طرح رس بس گئے ہیں اورہماری فکرونظر میں جدید مغربی محرکات وعوامل کے ساتھ غالب کے افکاروبصائر اس قدرسرایت کئے ہوئے ہیں کہ ان کوتحلیل کرکے الگ نہیں کیاجاسکتا اورانگلی رکھ کر ان کی نشاندہی ناممکن ہے۔ آج اردو کا کون سخنور یانثر نگار ہے جویہ دعویٰ کرسکے کہ وہ غالب کے اثر سے یکسربے نیازہے۔
یہ کہناغلط ہے کہ ادب میں ترقی پسندتحریک کمیونسٹ یااشتراکی تحریک کا بدلاہوا روپ ہے۔ جن لوگوں کواس زمانہ میں ترقی پسند ادیب سمجھا گیا یا جنہوں نے خود اپنے کوترقی پسند سمجھا ان میں بہت کم ایسے تھے جوکمیونسٹ پارٹی سے کوئی واسطہ رکھتے ہوں یاجنہوں نے کمیونزم کے نظریہ او ردستور کامطالعہ کیا ہواوران کوسمجھا ہو۔ جو ادیب یا شاعری کسی نئے خیال یامیلان کا جرأت کے ساتھ فنکارانہ اسلوب میں اظہارکرتا تھا وہ ترقی پسند سمجھا جاتاتھا۔ ہاں ان نئے میلانات وخیالات میں وہ نقطہ نظر غالب اور حاوی ہے جس کومارکسیت کہتے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیاجاسکتاکہ ترقی پسند تحریک اورکمیونسٹ پارٹی کا قیام دونوں ہم تاریخ ہیں اور موخذالذکر کاگہراپرتوترقی پسند ادب پرپڑتا ہے۔ یہ قدرتی بات ہے جوکسی رو سے قابلاعتراض نہیں۔
کمیونسٹ پارٹی کے معماروں اورانجمن ترقی پسند مصنفین کے بانیوں میں سبھی لوگ داناوبینا تھے اورتخلیق یاتنقید یادونوں کی قومی صلاحیتیں رکھتے تھے۔ ان میں کچھ ان صلاحیتوں کاوقتا فوقت ثبوت بھی دیتے رہتے تھے۔ بعض نے یادگار افسانے اور تنقیدیں لکھی ہیں اور اس وقت کے نوجوانوں کونئی سمتیں اورنئے راستے دکھائے ہیں لیکن ان کا براولین میں کوئی شاعرنہیں تھا یا اگرکوئی شعر کہنے کی قابلیت رکھتا بھی تھا تو اس نے شعرنہیں کہے۔ سجادظہیر، پروفیسر احمدعلی، ڈاکٹر علیم، رشیدجہاں، ڈاکٹراشرف، ڈاکٹراخترحسین رائے پوری نے جوعلمی اور ادبی خدمات اس دور میں انجام دیں وہ اگرچہ کم حجم ہیں مگر ان کوفراموش نہیں کیاجاسکتا۔
انہیں دنوں میں تین نئے شاعرو ں کے چرچے ہونے لگے جوکسی خاص گروہ سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں۔
بہرحال شاعری میں پیش قدم تھے۔ اقبال سہیل، فراق گورکھپوری اورجمل مظہری ان میں بزرگ سالی کی بنا پراقبال سہیل کوتقدم حاصل ہے۔ ان کی شاعری انداز فکر عبارت لہجہ ہراعتبارسے ان اوصاف واوضاع سے مرکب ہے جن کوغالب اور فارسی کے ان متغزلین سے منسوب کیاجاتار ہاہے جن کی پیروی خود غالب کے لئے باعث فخرتھی۔ رگھوپتی سہائے فراق بیسویں صدی کی دوسری دہائی میں اچھی مشق بہم پہنچاچکے تھے اورشاعروں میں ان کی آواز غور سے سنی جانے لگی تھی۔ لیکن ان کی شہرت اورجواں سال ذہنوں پران کا اثر۱۹۳۰ء کے بعد سے شروع ہوا۔ وہ مشرق اورمغرب کے ممتازترین مفکروں اورشاعروں کی روح اپنے اندرجذب کئے ہوئے ہیں۔ ویدانت کولرج اور ورڈسورتھ کے نظام فکر سے وہ خاص طور پر متاثرہیں۔ اردوکے سبھی شاعروں سے انہوں نے کچھ نہ کچھ حاصل کیاہے لیکن فکرواسلوب دونوں میں ان کی شاعری غالب کے گہرے اور مستقل نقوش لئے ہوئے ہے۔ فراق آج تک اردوکے نوجوان شاعروں خصوصیت کے ساتھ غزل کے شاعروں کومتاثر کررہے ہیں۔ جمیل مظہری شاعرکی حیثیت سے ۳۵۔ ۱۹۳۴ء میں ابھرے۔ ان کی شاعری میں خستگی میر کی ہے، روانی انیس کیہے لیکن تفکر اوربیان کی بلاغت کے ساتھ ندرت غالب کا فیض ہے۔ اوریہ ہوناتھا اس لئے کہ وہ وحشت کلکتوی کے ارشدتلامذہ میں سے ہیں۔
نئے شاعروں کی دوسری پود میں علی سردارجعفری مجاز، فیض، احمدندیم قاسمی، معین احسن جذلی کے نام سرفہرست آتے ہیں۔ یہ سب کے سب یاتو براہ راست اورواضح طورپرترقی پسندتحریک کی نہایت کرتے ہیں یا کسی نہ کسی حد تک تحریک سے متاثرہیں لیکن ان میں سے کوئی ایسا نہیں جوغالب کے چھوڑے ہوئے ترکہ کا حصہ دار نہ ہو۔
علی سردار کا مزاج رزمیہ ہے اوران کا لہجہ رجزیہ ہوتاہے۔ انہوں نے متقدمین اورمتاخرین اوراپنے بزرگ معاصرین کا ذکاوت کے ساتھ مطالعہ کیاہے اورپھر جدید مغربی حکما اور شعرا سے بھی وہ متاثرہیں۔ اس مطالعہ سے ان کی شاعری کی تربیت ہوئی ہے۔ ’’پرواز‘‘ کی بیشتر نظمیں اور ’’نئی دنیا کوسلام‘‘ کے اکثر ٹکڑے للکاریا جے جے کار ہوتے ہوئے بھی شاعری کے اچھے نمونے ہیں۔ علی سردار کے برعکس مجاز سراپاتغزل ہیں۔ ان کے اشعار بانسری کی آوازکی تاثیر ہوتی ہے جو دل میں اترکرسننے والے کوریشہ ریشہ میں سرایت کرجاتی ہے۔ وہ فانی اورجگر سے کافی متاثرہیں لیکن نہ فانی کی طرح مرگ اندیش ہیں نہ جگر کی طرح فکر وتامل سے خالی۔ ان کی شاعری تفکر اور تاثر کی خوش آہنگ آمیزش ہے۔ ان سے اردوغزل میں ایک ایسے میلان کی ابتدا ہوتی ہے جوقدیم سے بے تعلق نہ ہوتے ہوئے اپنے اندر کئی کشش رکھتاہے اورجس کو نورومانیت (NEO۔RAMANTICISM) کہناچاہئے۔ مجازغزل اور نظم دونوں میں ایک ایسی نئی آوازہیں جولطف ہوتے ہوئے بھی گمبھیر ہے۔ جان نثار اختربھی اسی نورومانی دبستان کے شاعر ہیں لیکن ان کی شاعری میں دیسی متن گداختگی نہیں ہے جومجاز کا امتیازی وصف ہے۔ جذبی بنیادی طورپر غزل کے شاعرہیں۔ وہ الفاظ کے انتخاب اوران کی ترکیب میں اہتمام اوراحتیاط سے کام لیتے ہیں لیکن ان کی شاعری ہمارے اندر نامرادی اور حرمان کے احساس کو تیزکردیتی ہے۔ فیض احمدفیض کی شاعری میں وہ انحنایا ترچھاپن سلیقہ کے ساتھ ملتاہے جو فن کوفن بنانے کے لئے ضروری ہے اور جس پر خواہ مخواہ علی سردار نے ایک مرتبہ اعتراض کیاتھا۔ اسی انحنا کا دوسرا نام استعاریت یارمزیت ہے جوغالب کی بھی ایک نمایاں اورمنفرد صفت ہے۔ فیض کے اشعار فنی لطافتوں کے ساتھ زندگی کے نئے تموج کا پتہ دیتے ہیں۔ وہ مدہم لہجہ میں ہمارے اندر موجودمعاشرے سے ناآسودگی اورمسلسل انقلاب کی ناگزیری کا احساس پیدا کرتے ہیں مگرشعرکوتبلیغی نعرہ نہیں ہونے دیتے۔ انداز بیاں میں اپنے معاصرین میں وہ غالب سے زیادہ قریب نظرآتے ہیں۔ وہ خودبھی غالب کے انداز کی فارسی ترکیبیں تراشتے رہتے ہیں جس کے ان کے اشعار میں نیاپن قائم رہتا ہے۔ فیض کی شاعری میں تیسرا بعد یعنی بلندی یا گہرائی اتنی نہیں ہوتی جتنی ان سے توقع کی جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ان کے یہاں فکری حجم کم ہوتا ہے۔ ان کی شاعری اشاروں کی شاعری ہے۔ احمدندیم قاسمی اپنے دور کے انتشار واضطراب کوشعر بنیادینے کی اچھی مہارت رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری زندہ رہنے اور مقابلہ کرنے کی تاب پیدا کرتی ہے۔ وہ اقبال کے توسط سے غالب سے متاثر ہیں۔ اسی زمانہ میں نشور واحدی اورمجروح سلطان پوری نے اردوغزل کونئی نزاکتیں دیں اور اس میں تازہ نکھارپیدا کیا۔ دونوں اپنے اپنے انفرادی طورسے غالب کی آواز کے ارتعاشات اپنی شاعری میں جذب کئے ہوئے ہیں۔
دوسری عالمی جنگ کے آخری برسوں سے اب تک اردو میں ایسے نئے شاعروں کی تعدادبہت ہے جنہوں نے ہماری شاعری کونئے خیالات ورجحانات سے مانوس کیا ہے اوراسلوب بیان میں تازہ کیفیتیں پید ا کی ہیں۔ ان کی عمر یں تقریبا پچاس سے بیس سال تک کی ہیں۔ یہ شعرا مختلف فکری مکاتب سے تعلق رکھتے ہیں اور برصغیر کی دونوں مملکتوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس دوران میں اردوغزل پابند نظم آزاد نظم میں کامیاب کوششیں ہوتی رہی ہیں جو یادگار تخلیقی تجربات کا مرتبہ رکھتی ہیں۔ ان تمام فکری اوراسلوبی تغیرات وتنوعات میں جب ہم کسی تاریخی سرچشمہ کی تلاش کرتے ہیں توہم کوغالب ہی پررکناپڑتاہے۔ غالب کے ساتھ ابتک ہم ایک قومی تاریخی یگانگت پاتے ہیں۔
غالب کس طرح اورکس حد تک ہمارے تفکر اور اظہار میں ایک زندہ اور فعال قوت بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علامات وشواہد کا کافی جائزہ لیاجاچکاہے لیکن بعض سامنے کی باتیں رہ گئی ہیں۔ یہ کچھ حیرت کی بات نہیں کہ غالب کی خارج آہنگی اور مشکل پسندی کے باوجودمیرسے داع اورامیر تک کے مشاہیر کے اشعار کی طرح یا شاید ان سے زیادہ ہی غالب کے اشعارذوق سخن رکھنے والوں کی زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں۔ ضرب المثل اشعار میں غالب کے اشعار کی تعداد کم نہیں ہے۔ اگرمثالیں اکٹھا کی جائیں تو ایک بیاض تیارہوجائے۔ ان میں سہل الممتنع مشکل درمیانی ہرقسم کے اشعار ہوں گے۔ اس کے علاوہ تربیت یافتہ لوگوں کی صحبتوں علمی اور ادبی تقریروں اورتحریروں میں کتنے فقرے استعمال ہوتے رہتے ہیں جوغالب سے لئے گئے ہیں۔
اسی سلسلہ ایک اوربات قابل غورہے جس کی طرف دھیان کم ہوجاتاہے۔ گزشتہ پچاس سال کی مدت میں اردوکے کتنے شاعر اورنثرنگاروں نے اپنی کسی ایک تخلیق یا کئی تخلیقات کے مجموعوں کے جونام رکھے ہیں وہ غالب کے اشعار ہی سے لئے گئے ہیں۔ سب سے پہلے جومثال یادآتی ہے وہ اردوکاایک ڈراما ہے جس کواپنی جوانی میں عبدالماجد دریابادی نے ’’ناظر‘‘ کے فرضی نام سے لکھا تھا۔ اس کا عنوان ’’زودپشیماں‘‘ ہے۔ پھرعبدالماجد دریابادی ہی نے ان کی تبلیغ کرنے والے ایک انگریز کی تصنیف کا ترجمہ کیااور اس کا نام ’’پیام امن‘‘ رکھا۔ عبدالماجددریابادی کے اسلوب نگارش میں جو کشش ہے اس کا رازبھی یہی ہے کہ اس پر غالب کا اثر ہے۔ یہ اوربات ہے کہ اس میں محمدحسین آزاد اور نذیراحمد کا رنگ بھی قرینہ کے ساتھ ملا ہواہے۔ رشید احمدصدیقی کے ایک مضمون کا عنوان ’’پاسبان’‘ ہے جو بالقصد غالب کے ایک شعرسے ماخوذہے۔ ان کے خاکوں کے ایک مجموعہ کا نام ’’گنجہائے گراں مایہ‘‘ اور درس گاہ علی گڑھ سے متعلق ایک طویل مضمون کا نام ’’آشفتہ بیانی میری‘‘ ہے۔ اس سے اندازہ کیاجاسکتا ہے کہ رشیداحمد صدیقی کے ذھن پر غالب کتنا چھائے ہوئے ہیں۔ ان کی عبارت میں بھی غالب کی پرکاری ہوتی ہے لیکن اس پرکاری میں سادگی اوربیساختگی کی جگہ تکلف اوراہتمام ہوتاہے۔
راقم الحروم نے ۱۹۳۰ء میں اپنے افسانوں کے مجموعہ ’’خواب وخیال‘‘ کے لئے جب مقدمہ لکھا تواس کا عنوان’’ناچارمسلمان شو‘‘ اورجب اپنا ایک طویل افسانہ کتابی صورت میں شائع کرایا تو اس کا نام ’’عیدزبوں‘‘ رکھا۔ شاہداحمد دہلوی کے خاکوں کانام ’’گنجینہ گوہر‘‘ ہے۔ فیض احمد فیض کے کلام کے دومجموعے ’’نقش فریادی‘‘ اور ’’دست تہ سنگ‘‘ کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ علی جواد زیدی کسی زمانہ میں ترقی پسندوں میں شامل تھے بعد کوسرکاری عہدہ قبول کرلیا۔ ان کا مجموعہ ’’رگ سنگ‘‘ ہے۔ ڈاکٹرخورشید الاسلام کی نظموں کا نام ’’رگ جاں‘‘ ہے۔ جوگندرپال نے اپنی کتاب کا نام ’’ایک بوندلہوکی‘‘ رکھاہے۔ عزیزحامدمدنی کے منظومات کا مجموعہ ’’دشت امکاں‘‘ کے نام سے شائع ہواہے۔ عبدالعزیز خالد نے اپنے ایک مجموعہ کا نام ’’ماتم ایک شہرآرزو‘‘ پسند کیاہے۔ اخترجمال کے ناول کا نام ’’انگلیاں فگاراپنی‘‘ ہے۔ حافظہ پرزوردیا جائے یا تلاش وتحقیق سے کام لیاجائے تو ابھی نہ جانے کتنی مثالیں مزیدسامنے آئیں گی اورفہرست خاصی طویل ہوجائے گی۔
غالب فطرت کی طرف سے نت نیاذہن لائے تھے یااگر نیازفتح پوری کی اصطلاح استعمال کی جائے تو انہوں نے اب سے کوئی پچپن سال پہلے ٹیگور کی ’’گیتان جلی‘‘ کا ترجمہ کرتے ہوئے تراشی تھی توکہا جاسکتا ہے کہ فطرت نے غالب کو دائم الجدت (ETERNALLTY NEW) ذہن عطا کیاتھا۔ وہ اپنے زمانہ کے لئے نیاذہن تھے۔ آج بھی ہم ان کوایک نیا دہن پاتے ہیں اورہر اس آنے والے دور کے لئے وہ نیا ذہن رہیں گے جس کاتصر کیاجاسکے۔ اسی لئے ہرنئے دورکا جدید سے جدید ذہن اپنے کوغالب سے قریب اورمانوس پاتارہاہے اورغالب کاانداز فکر اور شیوہ گفتار ا س کی تخلیقی قوت کومتحرک کرتا رہتاہے۔ غالب ایک ایسا سرچشمہ الہام ہیں جوکبھی ختم نہیں ہوسکے گانہ اپنی فطرت اور تازگی کھوسکتاہے۔ ان کی نوائے آشفتہ ’’نوائے سروش‘‘ ہے جو ہرزمانے میں سنی جائے گی اورجو ہر نسل کے توانا اورصالح نوجوانوں کو زندگی اورتوانائی کانیاپیغام دیناسکھائے گی۔
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.