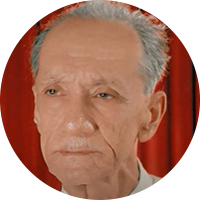غالب: فکر و نظر
شعر غالب نہ بود وحی و نہ گوئیم ولی
تو و یزدان نتواں گفت کہ الہامی ہست؟
غالب نے نہ جانے کس خیال کے تحت وحی اورالہام کے اصطلاحی فرق کودرمیان میں لاناضروری سمجھا۔ ہم اس بحث کی موشگافیوں کوماہروں کے لئے چھوڑتے ہوئے اتناضررکہیں گے کہ اگرزمین پروحی اترسکتی ہے۔ اگرشہدکی مکھی کووحی ہوسکتی ہے کہ پہاڑوں اور درختوں پرچھتے بنائے تاکہ انسان کے لئے شفابخش مشروب مہیا ہوسکے توانسان تواشرف المخلوقات ہے، وہ بھی وحی کا حامل ہوسکتا ہے اورہوتارہاہے اور اگرمتقی کے نفس کوتقوی اورفاجر کے نفس کوفجور کاالہام ہوسکتا ہے توشاعر کے نفس کو شعرکابھی الہام ہوسکتاہے۔ وجود کے مختلف مدارج ہیں اورشعور کی مختلف سطحوں پر وحی یاالہام کی نوعیت اور اس کی غایت یا افادیت مختلف ہوتی ہے۔
میں اس سے پہلے بھی اس نکتہ کی طرف توجہ دلاچکاہوں کہ دنیا کی کئی مقتدرزبانوں میں ’’شاعر‘‘ کے مترادف جوالفاظ ملتے ہیں ان کے اصلی معنی ایسے ہی شخص کے ہیں جوتوفیق خداوندی یا امررب کا حامل ہو جو دانائے اسرارکائنات ہو، جو ایسی چشم بینا رکھتا ہو کہ ان حالات وعوامل او ران کے عواقب کودیکھ اورپہچان سکے جو ابھی عوام الناس سے پوشیدہ ہیں۔ عارف، حکیم، دانشورپیش ہیں۔ یہ ہیں ان زبانوں میں ان الفاظ کے معنی جوشاعر کی جگہ رائج رہے ہیں۔ انگریزی زبان میں (POET) جس یونانی لفظ سے مشق ہے اس کے معنی خالق، فاطر، صانع کے ہیں۔ شایدیہ نکتہ بجنوری کے ذہن میں تھا جب کہ انہوں نے کہا کہ آفرینش کی قدرت جو صفات باری میں سے ہے شاعر کوبھی ارزانی کی گئی ہے۔ جہاں ملائکہ کارخانہ ایزدی میں پوشیدہ حسن آفرینی میں مصروف ہیں۔ شاعریہ کام علی الاعلان کرتاہے۔ اسی تصور کے تحت رابرٹ براؤننگ نے خداکو ’’شاعر اکمل‘‘ کہاہے اور اسی لحاظ سے ڈاکٹربجنوری عالب کو ’’ایک رب النوع‘‘ تسلیم کرتے ہیں۔ قدیم لاطینی زبان میں ’’واتیز‘‘ (VATES) بنی اور شاعردونوں کے لئے استعمال ہوتاتھا۔ خود لفظ ’’شاعر‘‘ کے لغوی معنی ایسے مردآگاہ کے ہیں جو دوسروں کو نئی آگاہیاں دے سکے۔ شاعری پیغمبری کاجزوہے۔ یہ فارسی میں ضرب المثل قول ہے جوہمارے لئے بہت پرانا ہوچکاہے یا پھر سامنے کی بات ہے۔ ہم شعر کے سلسلے میں ’’آمد‘‘ اور ’’آوردہ‘‘ کی اصطلاحیں نہ جانے کب سے استعمال کرتے آئے ہیں۔ ’’آورد‘‘۔ محنت، کاوش، تکلف کا اکتساب ہے لیکن ’’آمد‘‘ جوشعر کی عنصر ماہیت ہے وہ بے اختیار اوربے ساختہ اندرونی تحریک ہے جس کا دوسرا نام وحی یا الہامی ہوسکتا ہے۔
دنیا میں بہت سے شعرایسے ہوئے ہیں جنہوں نے بلندآواز میں یازیرلب شاعری کوہاتف یاغیب کی آوازبتایاہے اور جب شاعری کو’’لطف دیوانگی‘‘ شدید جذبات کا بیساختہ سیلان ’لامتناہی باران نور‘‘ ’’پرآہنگ دیوانگی‘‘ جیسے مبہم فقروں سے تعبیرکیاگیاہے توبھی مفہوم وحی، الہام یا القاہی ہاہے۔ خانقاہ رشیدیہ(جون پوروغازی پور) کے مشہور سجادہ نشیں عبدالعلیم آسی بڑے برگزیدہ شخص اورباکمال شاعر گزرے ہیں۔ وہ شاعری کے بارے میں صاف صاف کہتے ہیں،
شعر گوئی نہ سمجھنا کہ مراکام کام ہے یہ
قالب شعر میں آسی فقط الہام ہے یہ
غالب نے بھی شاعری کو کبھی اشارہ میں کبھی صراحت کے ساتھ غیب ہی کی آواز بتایا ہے۔ ان کے ایک شعر کو میں عنوان بناچکا ہوں۔ اردومیں یہ مقطع خاصان غالب میں ضرب المثل ہے۔
آتے ہیں غیب سے یہ مضامیں خیال میں
غالب صریر خامہ نوائے سروش ہے
ملاعبدالصمد کوفارسی زبان میں اپنا استادمانتے ہوئے غالب کواصرار ہے کہ شاعری میں ’’مجھ کومبدأ فیاض کے سواکسی سے تلمذ نہیں ہے‘‘ ایک فارسی شعر میں کہتے ہیں،
آنچہ در مبدأ فیاض بود آن من است
گل جدا ناشدہ از شاخ بدامان مست است
اوراس شعر میں بھی اس خیال کا دوسرے پیریہ میں اظہارکیاگیاہے،
رنگ ہا درطبع ارباب قیاس آمیختہ
نکتہ ہا در خاطر اہل بیاں انداختہ
کلیات نظم فارسی کے آخرمیں جوتفریظ ہے اس میں ایک رباعی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خودغالب کے خیال میں ان کی ’’شوخی تاثیر‘‘ اور خوبی تقریرکا رازکیاتھا اوروہ اپنی شاعری کو کیاسمجھتے تھے۔
گردذوق سخن بدہر آئیں بودے
دیوان مراشہرت پردیں بودے
غالب اگر ایں فن سخن دیں بودے
آں دیں راایزدی کتاب ایں بودے
یہ یادرکھنا چاہئے کہ غالب نے اس رباعی میں اپنے جس ’’دیوان‘‘ کے بارے میں اظہارخیال کیاہے۔ وہ ان کے فارسی کلام کامجموعہ ہے۔ لیکن وہ اپنے اردو کلام کوبھی الہام سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ ان کاایک مشہو راردوشعرسناچکا ہوں۔ ایک دوسرا شعر سنئے جس سے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ شاعر اپنے کلام کو فتوحات سماوی سے بھی کچھ افضل سمجھتا ہے۔
پاتا ہوں داد اس سے کچھ اپنے کام کی
روح القدس اگرچہ مراہم زباں نہیں
انہیں اشارات کے زیراثر ڈاکٹرعبدالرحمن بجنوری کی زبان سے وہ جملہ نکل گیاجو اپنی جگہ خود بھی ایک الہامی قول کا حکم رکھتا ہے اورجواب تنقید غالب میں کلاسیکی حیثیت حاصل کرچکاہے۔
’’ہندوستان کی الہامی کتابیں دوہیں۔ وید مقدس اوردیوان غالب‘‘
غالب ان شخصیتوں میں سے ہیں جوفکرواظہار کی تاریخ میں معجزات یانئے آیات کی مترادف ہوتی ہیں جو ہم کونئی سمت میں موڑتی ہیں اورنیاراستہ دکھاتی ہیں۔ میں آج سے بہت پہلے کئی موقعوں پر غالب کو اردوکا پہلامفکرشاعر کہہ چکا ہوں مگرحقیقت یہ ہے کہ غالب بنیاد ی طورپر صاحب نظر اورمفکرہیں۔ ان کے کلام میں اردو ہویا فارسی ایک نیازاویہ نظر اورایک نیاانداز فکرملتاہے اورہمارا دعوی ہے کہ وہ جس زبان کے بھی شاعرہوتے فکروبصیرت میں اپنی انفرادیت اوریکتائی کی بددولت ممتازرہتے۔ ان کے فارسی اشعار جابجا درمیان میں آئیں گے اوران سے اندازہ ہوتا جائے گا کہ ہمارایہ دعویٰ کہاں تک حق بجانب ہے کہ غالب جس زبان کے بھی شاعرہوتے ہیں اپنی کائناتی بصیرت اورمعنی یاب فکرکی بنا پر ہزاروں میں پہچان لئے جاتے۔ فارسی میں بھی غالب کے بہت سے اشعار ایسے ہیں جونئے انکشافات کا درجہ رکھتے ہیں لیکن آئیے تھوڑی دیر کے لئے ہم ان کی اردشاعری تک اپنی نظرمحدود رکھیں اور دیکھیں کہ اردو کو ان کی شاعری نے کیادیا۔ غالب سے پہلے اردوغزل یا توخالص جذبات کی شاعری تھی اور اس میں داخلیت کازورتھا اور اس داخلیت میں بھی انفعالیت کی فضاچھائی ہوئی تھی یا پھرمصحفی اورجرأت کی خارجی واقعیت کوقبول عام حاصل تھا لیکن خود غالب کے زمانہ میں دبستان ناسخ کی شاعری سے زیادہ مقبول ہورہی تھی جو دورازکامضمون آفرینی اور لفظی زورآزمائی کے سواکچھ نہ تھی۔ غالب نے اردو غزل کو مجہول داخلیت اور سطحی خارجیت دونوں کے تنگ دائروں سے نکال کوفطرت انسانی سے قریب کردیا اور خوداپنی مشکل زبان اورپیچیدہ طرزبیان کے باوجوداردوشاعری کوبڑھتی ہوئی جسامت سے بچاکر اس سے اندرمعنوی حجم پیدا کیا۔ دنیاکے عظیم مفکرادیبوں کی ایک پہچان یہ بھی رہی ہے کہ وہ اپنی فکرتی بصیرت سے ان الفاظ کے نئے ابلاغی امکانات کوپالیتے ہیں جوصدیوں سے استعمال ہوتے آئے ہیں اور ان کوزندگی کے نئے رموزونکات اظہار کے لئے نئے قرینے سے استعمال کرکے ان کی معنویت کوبڑھادیتے ہیں۔ غالب نے بھی یہی کہا ہے اوران کوخوداس کااحساس ہے۔ ایک قصیدہ میں جونعت اورمنقبت پرمشتمل ہے کہتے ہیں۔
لفظ کہن و منعی نو در ور ق من
گوئی کہ جہان است و بہار است جہاں را
غالب دنیا کے ہربڑے شاعر کی طرح بنیادی طورپر داخلی صنف کے شاعر تھے اور اس صنف میں بھی اس تحتی صنف کے شاعر تھے جس کوغزل کہتے ہیں اور جوفارسی اوراردو کے سوادنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے۔ کہا جاتاہے کہ غزل میں کوئی وحدت نہیں ہوتی۔ یہ سچ ہے کہ غزل کا ہرشعر ایک مکمل اورمنفردمضمون اوراپنی جگہ ایک اکائی ہوتاہے اور بظاہر پوری غزل میں کوئی وحدت نظر نہیں ہوتی لیکن حقیقتا اس میں بڑی دقیق وحدت ہوتی ہے اور یہ وحدت مرکب اور پیچیدہ ہوتی ہے۔ پہلی بات تویہ ہے کہ ایک غزل ایک ہی شاعر کی کہی ہوتی ہے او ر اس کے مزاج کی کئی رخ سے آئینہ دار ہوتی ہے۔ غزل سے شاعر کی پوری فردیت کا اندازہ لگایاجاسکتاہے۔ پھر غزل میں قافیہ کی وحدت ہوتی ہے اورسب سے پہلے تو اس سے یہ پتہ چل جاتاہے کہ کون صرف قافیہ بندشاعر ہے اور کس کاذہن ایک قافیہ سے کسی خاص معنی کی طرف منتقل ہوتاہے۔ قافئے ایتلافات ذہنی (MENTAL ASSOCIATIONS) کا بہترین امتحان ہیں اور ان سے شاعر کے پورے شعو رکا قیاس کیاجاسکتا ہے۔ میں نے علی گڑھ میں ایک مرتبہ ایم اے کے طلبا سے کہا تھا کہ شعو رکی رو (STREAM OF CONSCIOUSNESS) کوسمجھنے کے لئے دورجانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی نہایت معصوم اور بے ساختہ مثال غزل ہے۔ ہم مجمل طورپرکہہ سکتے ہیں کہ غزل میں ’’شعورکی رو‘‘ کی وحدت ہوتی ہے۔
ایک ماہرمطرب تارکے پہلے ارتعاش سے پورا راگ پالیتاہے۔ ایک حاذق طبیب نبض کی ایک دھڑکن سے نبض کا پورا آہنگ معلوم کرلیتاہے۔ اسی طرح کسی شاعر کے ایک شعر سے صحیح ذوق وادراک رکھنے والے اس کے پورے شعری کردار کا پتہ چلاسکتے ہیں۔ غالب نے بڑی سچی بات کہی ہے۔
غالب بہ قدر حوصلہ باشد کلام مرد
باید زحرف نبض حریفاں شناختن
غالب کے اشعار کا اگرتامل کے ساتھ مطالعہ کیاجائے تویہ محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے حقائق اور معاملات ومسائل کے بارے میں شاعر کا ایک مستقل فکری میلان ہے جواستفسار وتفتیش کا نتیجہ ہے۔ غالب کوآفرینش کائنات اور حیات انسانی کے تمام رموزواسرار کاپورا ادراک حاصل ہے اوروہ ان کوبیک وقت حکیمانہ اور فن کارانہ سلیقہ کے ساتھ نازک اشاروں میں بیان کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ تحلیق اورکائنات کے نکات ہوں یا انسانی زندگی کے مسائل یا انسانی قلب ودماغ کے واردات وکیفیات غالب ان کوصرف بیان کرکے نہیں رہ جاتے بلکہ ان پرمتفسر انہ نظرڈالنا اور غورکرنا سکھاتے ہیں۔
غالب زندگی کے شاعر ہیں اورزندگی کے ہرپہلو اوراس کی ہرسطح کے شاعر ہیں۔ شاعر کی سب سے بڑی بلندی یہی ہے کہ وہ بلندترین سطح پرپہنچنے کے بعدبھی انسانی زندگی اور انسانی شعو رکی پست ترین منزلوں ں کوبھول نہ جائے بلکہ ان کوبہرحال نظر میں رکھے۔ غالب کے اردودیوان میں جہاں اس قسم کے حکیمانہ اشعار ملتے ہیں۔
شکوہ و شکر کو ثمر بیم و امید کا سمجھ
خانہ آگہی خراب دل نہ سمجھ بلا سمجھ
یا
نظر میں ہے ہماری جادہ را ہ فنا غالب
کہ یہ شیرازہ ہے عالم کے اجزائے پریشاں کا
جہاں ایسے مہذب اور لطیف انداز کی معاملہ بندیاں ہیں۔
ابھی آتی ہے بوبالش سے اس کی زلف مشکیں کی
ہماری دید کو خواب زلیخا عار بستر ہے
یا
نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی ہیں
تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشاں ہوگئیں
وہیں اس طرح کے اشعار بھی نظرآتے ہیں جوتربیت یافتہ ذوق کوگراں گزرتے ہیں اور جواگرغالب کے دیوان میں نہ ہوتے تو وہ غالب سے کبھی نہ منسوب کئے جاسکتے۔
دھوتا ہوں جب میں پینے کو اس سیم تن کے پانو
رکھتا ہے ضد سے کھینچ کے باہر لگن کے پانو
اسد خوشی سے مرے ہاتھ پانو پھول گئے
کہا جو اس نے ذرا میرے پانو داب تو دے
ایسی مثالیں فارسی کلام میں نہیں ملتیں اوراردودیوان میں، خال خال ہیں لیکن اس کاراز وہی ہے جس کی طرف اشارہ کرچکاہوں یعنی غالب زندگی اور شعور زندگی کی کسی سطح کے حالات وتجربات کے اظہار میں قاصرنہیں تھے۔
کسی شاعری یادانشور کے فکری نظام کے سلسلے میں سب سے پہلے جو سوال ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات تحلیق کائنات، تخلیق کاسبب اور اس کی غایت کے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے اس لئے کہ بڑے سے بڑا ملحد بھی اس سوال پر اچھی طرح غور کرنے کے بعدہی اپنے الحاد تک پہنچتاہے۔ غالب کا بھی اس باب میں ایک واضح تصور ہے۔ یہ کہاجاچکاہے کہ غالب اپنے عہد کی مخلوق بھی تھی اور ایک نئے عہد کے خالق بھی۔ وہ روایت عظمی کوتسلیم بھی کرتے تھے اوراسکی تحسین وتہذیب کے لئے جدت کوبھی ضرورسمجھتے تھے۔ وہ تقلید واجتہاد دونوں کے بیک وقت قائل تھے۔ پہلی صحبت میں غالب کو ایک نابغہ تسلیم کیاجاچکا ہے اور نابغہ اپنے زمانے سے بہت آگے ہوتا ہے لیکن وہ اس سے بے تعلق نہیں ہوتا اگرایسا ہوتو وہ اپنے زمانے کوکوئی نیاپیغام نہیں دے سکتا۔ وہ اپنے زمانہ کے توانا اور صالح عناصر کو سمیٹ کرآگے بڑھتاہے۔ وہ اپنے زمانہ کے اصلاحات ومحاورات میں لوگوں کومخاطب کرکے اپنااپناپیغام سناتاہے۔ اس لئے اس کے مخالفین بھی اس کو سمجھتے ہیں۔ غالب بھی مستقبل کے مبصرہونے سے پہلے اپنے ماحول کی مخلوق تھے اورجہاں تک تخلیق کائنات خالق اورخلقت کے رشتہ کاتعلق ہے اس زمانہ کا سب سے زیادہ مقبول رجحان وہ تھا جس کووحدت الوجود کہتے آئے ہیں۔ حالی سے لے کر اب تک غالب کے جتنے ناقدگزرے ہیں سب نے غالب کوصوفی اور موحدہی بتایاہے۔ خود غالب نے اپنے کو ’’موحد‘‘ کہاہے اوراپناکیش ترک رسوم بتایاہے۔ ان کواپنے مسائل تصوف اور ان کے بیان پربڑاناز ہے۔ فارسی اور اردو میں ان کے بہت سے اشعار پیش کئے جاسکتے ہیں جوغالب کے دعوے اورناقدین کے خیال کی تائید کرتے ہیں مثلاً،
اسے کون دیکھ سکتا کہ یگانہ ہے وہ یکتا
جو دوئی کی بو بھی ہوتی توکہیں دوچارہوتا
یہ شعر غالب کے مشہو ر ترین اشعار میں سے ہے اور اتنی بار پڑھا اورسنایاجاچکا ہے کہ اگرکوئی اسے فرسودہ کہہ کرٹال دے وہ معاف کیاجاسکتا ہے۔ لیکن غالب کی ایک ممتاز صفت یہ ہے کہ ان کے اشعارکبھی فرسود ہ نہیں ہوپاتے بلکہ ان کو جب بھی پڑھئے آپ کو اس میں تازگی محسوس ہوگی۔ اس شعر میں غالب کا نظریہ توحید کچھ مبہم طورپر محی الدین ابن العربی کے نظریہ سے ملتا ہے۔ غالب نے ایک پامال محاورے (دوچارہوتا بہ معنی دکھائی دیتا) کوبڑے منفرد اندازمیں استعمال کرکے ایک حکیمانہ نکتہ بیان کیاہے جودواور دوچا رکی طرح ایک بدیہی حقیقت ہے۔ ایک کوایک سے ضرب دیتے جائیے وہ اب تک ایک رہے گا۔ وحدت ہمیشہ وحدت رہے گی لیکن ایک میں کسراقل کابھی اضافہ کرکے اس کو اسی سے ضرب دیتے جائیے ا س میں تعددبڑھتا جائے گا۔ وحدت میں کثرت پیدا ہوتی چلی جائے گی اورتکاثر کایہ سلسلہ غیرمختتم رہے گا۔ دوسے چار اور چار سے سولہ اور سولہ سے دوسوچھپن اوریہ سلسلہ الی غیر النہایت جاری رہے گا۔ شعر میں ایک اورنکتہ ہے۔ غالب صرف ایک ذات کوموجود سمجھتے ہیں دوسری کوئی ذات موجود نہیں۔ پھر کون دیکھے اور کس کودیکھے۔ دیکھنے کے لئے کم سے کم دوذاتوں کے وجود کوتسلیم کرناپڑے گا۔
اسی خیال کوغالب نے ایک دوسرے شعر میں بھی ظاہرکیاہے،
اصل شہود و شاہد و مشہودایک ہے
حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حسا ب میں
ایک فارسی شعر میں کہتے ہیں،
جلوہ ونظارہ پنداری کہ ازیک گوہر است
خویش رادر پردہ خلقے تماشاکردہ
یہی تصورایک اردوقصیدہ کے مشہور مطلع میں زیادہ دلپذیر اندازمیں پیش کیاگیاہے۔
دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں
ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بیں
کچھ اشعار اوراسی قبیل کے سن لیجئے جو دحدت الوجود ہی کے نظریہ کے حامل ہیں،
دل ہرقطرہ ہے سازاناالبحر
ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا
ہے کائنات کوحرکت تیری ذات سے
پر تو سے آفتاب کے ذرہ میں جان ہے
ہے تجلی تری سامان وجود
ذرہ بے پر تو خورشید نہیں
عالم از ذات جدا نبود ونبود جزذات
ہمچورا زے کہ بود در دل فرازانہ نہیں
مثنوی ’’ابرگہربار‘‘ کے یہ دواشعار اسی عنوان کے تصوروحدت کا اظہار کرتے ہیں جن کوہم اکابر مسلک وحدت الوجود سے منسوب کرتے آئے ہیں۔
جہاں چیست آئینہ آگہی
فضائے نظر گاہ وجہ اللہی
بہ ہرسو کہ روآوری سوئے اوست
خود آں روکہ آوردہ روئے اوست
چوں ایں جملہ راگفتہ عالم اوست
بگفت آنچہ ہرگز نہ آید ہم اوست
اوریہ شعر بھی بڑا بلیغ اورکیف آگیں ہے،
ہے وہی بدمستی ہرذرہ کا خود عذرخواہ
جس کے جلوے سے زمیں تا آسماں سرشار ہے
لیکن غالب اپنے طبعی تامل اور استفسار کوکیاکریں۔ وہ ان سچے لوگوں میں سے تھے جن کے دلوں میں کسی نقطہ نظر کوتسلیم کرلینے کے بعدبھی شکوک وسوالات رہ رہ کرابھرتے رہتے ہیں اورجوکبھی اپنے فطری میلان تفتیش وتفحص کے ساتھ ناانصافی نہیں کرسکتے۔ غالب وحدت الوجود کے نظریہ کوقبول کرچکے ہیں۔ وہ خدا کو ماسوایا ماسو کو خدا سے الگ تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود وہ حیرت کے عالم میں کہہ اٹھتے ہیں،
ہرچند ہرایک شئے میں گو ہے
پرتجھ سی توکوئی شئے نہیں ہے
یا سوال کرنے لگتے ہیں،
جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود
پھریہ ہنگامہ اے خدا کیاہے
یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں
غمزہ وعشوہ واداکیاہے
شکن زلف عنبریں کیوں ہے
نگہ چشم سرمہ کیاہے
لالہ وگل کہاں سے آئے ہیں
ابرکیا چیز ہے ہوا کیاہے
حالانکہ وہ تسلیم کرچکے ہیں کہ،
ہے رنگ لالہ و گل و نسریں جدا جدا
ہے رنگ میں بہار کا اثبات چاہئے
اوریہ بھی تلقین کر چکے ہیں کہ،
یعنی بہ حسب گردش پیمانہ صفت
عارف ہمشہ مست مئے ذات چاہئے
مرزابیدل کا بھی یہی مسلک ہے۔ مجاز کو حقیقت تک پہنچنے کے لئے پل بتایاگیا۔ اگرحقیقت کاکوئی وجود ہے تواس تک پہنچنے کے ذریعہ کے وجود کو بھی اصلی تسلیم کرنا پڑے گا۔ پھرصفات ومظاہرمیں یہ شکوک وسوالات کیسے؟
مرزابیدل اسی لئے سمجھاگئے ہیں،
نقوش اعتباردشمن ودوست
سواد نسخہ یکتائی اوست
اورپھر غالب یہیں شک اورسوال کی منزل پرنہیں ٹھہرتے بلکہ آگے بڑھ کراثبات اوریقین کی ایک ایسی دوسری منزل پرپہنچ جاتے ہیں جو منزل وحدت الوجود کی نفی معلوم ہوتی ہے۔ وہ خالق اور خلق اللہ اور غیراللہ، ذات اورصفات ومظاہر کوشریک ازلی اور دونوں کویکساں برحق مانتے ہوئے ہستی کو ’’فریب‘‘ اور تمام عالم کو ’’حلقہ دام خیال‘‘ بتاتے ہیں۔ یہ کیاہے؟ وہ تسلیم کرچکے ہیں کہ،
دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں
ہم کہاں ہوتے اگرحسن نہ ہوتا خودبیں
پھربھی وہ ماسوا کو ’’وہم‘‘ قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں،
اے زوہم غیر غوغا درجہاں انداختہ
گفتہ خود حرفے و خودرا درگماں انداختہ
یایہ شعر جس کی بلاغت کا اعتراف غالب کا مخالف بھی کرے گا۔
نہ ہوبہ ہرزہ بیاباں نورد وبم وجود
ہنوز تیرے تصور میں ہے نشیب وفراز
اگررب اورامررب برحق ہیں توامررب سے جوعالم موجودات ظہور میں آیا وہ ’’وہم‘‘ یا’’گمان‘‘ کیسے ہوسکتا ہے۔ جوابھی یہ دعوی کرچکاہے کہ،
قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن
ہم کومنظور تنک ظرفی منصور نہیں
وہ دوسری ہی سانس میں یہ کیسے کہہ سکتا ہے،
کہتے ہیں شاہد مطلق کی کمر ہے عالم
لوگ کہتے ہیں کہ ’’ہے‘‘ پرہمیں منظورنہیں
اسی قبیل کا ایک دوسرا شعر ہے،
ہاں کھائیو مت فریب ہستی
ہرچند کہ ’’ہے‘‘ نہیں ہے
غالب اس منزل پربھی قیام نہیں کرتے۔ وہ عالم اسباب وصور کو صرف وہم سمجھ کرمطمئن نہیں ہوتے۔ ان کوساری ہستی پرتضاد معلوم ہوتی ہے۔ تکوین میں فساد وفنا تخلیق میں زوال اورموت کے میلانات موجودہیں۔ ہستی کی فطرت میں نیستی ہے۔ غالب شناسوں میں یہ شعرمشہور ہے جونہ صرف ایک قدیم تصورکی ایک بالکل نئے اندازمیں ترجمانی کرتا ہے بلکہ اس جدلیت کی طرف ہمارے ذہن کو منتقل کرتاہے جوعام طورسے ہیگل اورمارکس کے ساتھ منسوب کی جاتی رہی ہے۔
مری تعمیر میں مضمر ہے اک صورت خرابی کی
ہیولیٰ برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا
اردومیں تقابلی تنقید کا آغازیوں توحالی، شبلی اورامدادامام اثرہی کے دور سے ہوگیاتھالیکن اپنے زمانہ کی نوجوان نسل میں اس میلان کواستوار اور رائج کرنے والے ڈاکٹرعبدالرحمن بجنوری ہیں جنہوں نے اپنے اجتہادی مصمون ’’محاسن کلام غالب‘‘ میں دنیاکا شایدہی کوئی بڑامفکر یا فنکار ایسا ہو جس سے غالب کا مقابلہ نہ کرڈالاہویا جس کے قول کاحوالہ نہ دیاگیاہو۔ یہ غالب کے ساتھ غلوکی حد تک بڑھی ہوئی عقیدت کا نتیجہ ہے۔ پھربھی ہم اتناتسلیم کریں گے کہ بجنوری کواس کا حق تھا۔ ان کوکئی زبانوں پرقدرت حاصل تھی اوران کا مطالعہ غیرمعمولی حد تک وسیع اورعمیق تھا اس لئے غالب کے سلسلے میں ان کودنیا کے دوسرے قدیم اورجدید اکابر کے فکری اجتہاد اورفنی اختراعات یاد آتے گئے تو کوئی قابل گرفت بات نہیں خود مجھے غالب کا مندرجہ بالا شعر جب جب یاد آیاہے تو زمانہ قبل سقراط کے یونانی حکیم ہرقلی طوس کے نظریہ حدوث سے لے کر ہیکل اورمارکس کے جدلیات اوربیرگسان کے تخلیقی ارتقا تک کی سرسری یادآتی رہی ہے۔ مگر یادو ں کی اس رومیں بہہ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے اصل موضوع کا سردشتہ ہاتھ سے جاتا رہتا ہے اور ’’طفیلی جمع شدچنداں کہ جائے مہیماں گم شد‘‘ والی بات ہوجاتی ہے۔
اس شعرکے سلسلے میں میں نے اتنی طوالت سے کام لیا اس پراگرغائرنظرڈالی جائے تویہ احساس ہوئے بغیرنہیں رہ سکتا کہ جس ’’حدوث غیرحادث‘‘ (CHANGELESS GHANGE) کوغالب ہستی کی فطری اورناگزیر خصوصیت تسلیم کرتے ہیں اس کوخلقت بالخصوص انسان کے حق میں کوئی مبارک بات نہیں سمجھتے۔ لہجہ سے صرف ٹپکتاہے کہ ان کے دل میں وہی خلش ہے جس کا کھل کر دوسرے شاعر نے یوں اظہار کیاہے،
اس سے بہتر تو یہی تھا نہ بنایا ہوتا
اورغالب کے اس زبان زد خواص وعوام شعر کو کیاسمجھا جائے جو قدیم سے قدیم اورجدید سے جدیداردودیوان غالب کے ہرنسخہ میں بسم اللہ کا حکم رکھتا ہے۔
نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا
کاغدی ہے پیرہن ہر پیکر تصویرکا
غالب خود اس شعرکامطلب سمجھاگئے ہیں اورہمارے لئے تذبذب یاکسی نئی تاویل کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ ہرنقش نقاش سے فریاد کررہاہے کہ اس نے اس کوبناکر وجود کی اذیتوں میں مبتلا کرکے کیوں چھوڑدیاہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نقاش صر ف اپنی شوخی تحریر کا اظہارکرناچاہتاتھا اوربس نقاش کواب اس سے سروکار نہیں کہ نقش پرکیا گزررہی ہے کائنات کا ذرہ ذرہ کراہ کراہ کرآفریدگار سے شکایت کررہا ہے کہ اس نے اس کوہستی کی کربناک آزمائشوں میں مجبور اوربے بس کرکے ایسی بے پروائی اورغفلت شعاری کیوں اختیارکرلی ہے۔ غالب کو ’’کارگاہ ہستی‘‘ کا ہرلالہ ’’داغ ساماں‘‘ نظر آتاہے اس شعر میں غالب انگریزی کے اس شاعر سے مختلف نہیں معلوم ہوتے جوکہہ گیاہے،
(ON THE CREATIION OF THY BEUTY HANGS THE MIST OF TEARS)
’’تیرے حسن کی کائنات پرآنسوؤں کاکہرا چھایا ہواہے‘‘
توکیا غالب مغرب کی بعض عظیم مفکروں اورادیبوں مثلا شوپنہار، لیوپارڈی، نووالس، طامس ہارڈی وغیرہ کی طرح تخلیق اورعالم ہست وبود کوایک ایسی قوت کانازل کیا ہوا عذاب سمجھتے ہیں جس نے سوچے سمجھے بغیرصرف اپنی قدرت کاتماشا دکھانے کے لئے اٹھارہ ہزار عالم کوپیدا کرکے ہیجان واضطراب میں چھوڑدیا۔ یا سارتر اور کامیو کی طرح وہ آفرینش کوکسی لایعقل قوت کی بے مقصد اور بے معنی حرکت کا اضطراری نتیجہ تصور کرتے ہیں جس کوانسان معقول اور بامقصد بنانے کی پیہم جدوجہد کی محنت وکاوش میں مبتلا ہے کیا وہ خرافاتی عہد کے یونانیوں کی طرح اس توہم کے حامی ہیں کہ دیوتاہم کو پیداکرتے ہیں اورپھر جس طرح کھیل میں شریراورناسمجھ بچے مکھیوں کومارڈالتے ہیں اسی طرح یہ دیوتااپنی تفریح اورتماشے کے لئے قسم قسم کی اذیتوں میں گرفتار کرکے آخرکار ہم کوفنا کردیتے ہیں۔
غالب کے اصل فکری میلان اوران کے مزاج کے باب میں ان میں سے کوئی حکم نہیں لگایاجاسکتا۔ یہ بتایا جاچکاہے کہ غالب نے متقدمین سے لے کر خودان کے عصر تک جتنے اکابروفن گزرے ہیں بالخصوص فارسی اوراردومیں ان سب کے کمالات کا احترام کیا ہے اوراپنے مزاج اوراپنے ظرف کے مطابق کم وبیش سب سے اثرات قبول کئے ہیں اورمجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسے ملکوں اورایسی زبانوں کے قدیم سے قدیم اورجدید سے جدیدمفکروں اورفنکاروں کے تصورات و تاثرات کے ارتعاشات بھی ان کے اردواورفارسی منظومات ومثنویات میں پائے جاتے ہیں جن کا علم ان کے بعدکی نسلوں کوتوبتدریج ہوتا گیا لیکن جن سے خودوہ براہ راست یا بالواسطہ قطعی ناواقف اورغیرمتعارف تھے اوریہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ حقیقت جوحسن اورخیرکو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ کسی ایک ملک یا کسی ایک زبان یا کسی ایک فرد کااجارہ نہیں ہے اورنہ وہ کسی خاص عہدیادورکی بلاشرکت غیرے جاگیر ہے۔ ایک ہی عہد یا دور کے مختلف افرادکو یا مختلف ملکوں مختلف زبانوں اورمختلف زمانوں کے مختلف افرادکوایک ہی حقیقت کی ایک ہی قسم کی جھلکیاں محسوس ہوسکتی ہیں بشرطیکہ وہ صاحب فکرونظر ہوں۔
غالب اپنے نصاب فکر میں بالکل منفردتھے۔ ان کافلسفہ کونیات (COSMOLOTY) یانظریہ وجودیات (ONTOLOGY) قدما اور خودان کے معاصرین اورعصرحاضر کے بعض ماہرین فنون لطیفہ اورفائقین دانش وحکمت کے ارتسامات وافکار سے قریب یادور کی مشابہت رکھتے ہوئے بھی سب سے مختلف ہے۔ غالب اس وحدت کے قائل تھے جواشراقیت اورمشائیت یعنی فلسفہ افلاطون اورفلسفہ ارسطو کے امتزاج کا نتیجہ تھی اورجس کا بانی یونان کامشہور حکیم فلاطینوس تھا اورجس کوکچھ ردقبول کے ساتھ کم وبیش دنیائے اسلام کے سارے بڑے حکما اورمشائخ نے اختیارکیا اور اس کوفروغ دیا۔
غالب ایک ذات واحد ایک ’’ہستی مطلق‘‘ کومانتے تھے جوہوالاول اورہوالآخر ہے۔ جو ساری کائنات کی روح ہے جوعلمت العلل بھی ہے اورغایتالغایات بھی۔ غالب بارباراصرار کے ساتھ دعوی پیش کرتے ہیں کہ وہ موجدہیں۔ وہ صوفی تھے، حکیم تھے، شاعرتھے۔ وہ عارف باللہ بھی تھے اور انسان اورانسانیت کی سچی معرفت بھی ان کوحاصل تھی جواس لئے زیادہ مشکل ہے کہ اس کے لئے انسان کی فطرت شناسی اور اس کے ساتھ قلبی ہمدردی درکار ہے۔
خالق اورخلق ذات اعلیٰ اورعالم مظاہرکے باب میں غالب کی فکر ونظر کی تین سطحیں اورتین زاویے تھے۔
غالب کا اساسی عقیدت وحد ت ہے۔ بہ قول خودوہ زبان سے لاالہ الااللہ کہت تھے اور دل میں لاموجودالااللہ لاموثرفی الوجود الا اللہ سمجھے ہوئے تھے۔ لیکن یہ وحدت خودازل سے اپنے اندرکثرت لئے ہوئے ہے جس کے بغیر وہ اپنے کو ظہورمیں نہیں لاسکتی۔ ذات او ر اس کے صفات ومظاہر، وجوب اورممکنات، قدم اور حوادث، لازم وملزومات کی حیثیت رکھتے ہیں اور دونوں حقیقی ہیں۔ لیکن کثرت صفات ومظاہر، ممکنات وحوادث صرف ملزومات میں جولازم سے الگ کوئی وجود نہیں رکھتے۔ پرچھائیں یاعکس مادی حقیقتیں ہیں لیکن ذات لازم سے جداہوکر ان کا کوئی وجود نہیں۔ اس باہم تناقص لیکن باہم متلازم تصور کو سمجھنا اور اس طرح الفاظ کا جامہ پہناکر دوسرے بھی کچھ سمجھ سکیں آسان کام نہیں۔
غالب ساری کائنات میں ایک روح کارفرماپاتے ہیں۔ ان کوتمام مظاہر وحوادث کے بطن میں ایک ’’ہویت‘‘ (IDENTITY) محسوس ہوتی ہے۔ ایک شعر سنئے جوانگریزی کے مشہور شاعر فطرت ورڈسورتھ کی کچھ یاددلاتاہے،
وہی اک بات ہے جویاں نفس واں نگہت گل ہے
چمن کا جلوہ باعث ہے مری رنگین نوائی کا
اس جدلیت اس کثرت میں وحدت اوروحدت میں کثرت کوشاعر نے اپنے اردو اورفارسی کلام میں جابجا نت نئے پیرائے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے جن میں سے کچھ اس صحبت میں سناچکاہوں لیکن غالب نے جس جس انداز سے اس پیچیدہ تصورکواپنی فارسی مثنوی ’’ابرگہربار‘‘ میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے وہ اپنی نظیر آپ ہے۔ یہ مثنوی نامکمل ہوتے ہوئے خاصی طویل ہے اورطویل اورنامکمل ہونے کے باوجود شاہکارہے۔ کچھ منتخب اشعارہی پیش کرنااس وقت ممکن اورمناسب ہے۔
چوپیدا تو باشی نہاں ہم توئی
اگر پردہ باشد آں ہم توئی
چہ باشد چنیں پردھا ساختن
شگافے بہ ہر پردہ انداختم
بدیں روئے روشن نقاب از چہ رو
چوکس جز تونبود حجاب از چہ رو
ہمانا ازاں جاکہ توقیع ذات
بود فرد فہرست حسن صفات
تقاضائے فرماں روائی دروست
ظہور شیون خدائی دروست
پھر ان شیوان کی تفصیل ہے جن میں یہ ’’جمال وجلال‘‘ اپنے کوظاہرکرتاہے۔
بہ گردوں زمہر و بہ اخترزتاب
بہ دریا موج و بہ گوہر ز آب
بہ انسان زنطق و بہ مرغ از خروش
بہ ناداں زوہم و بہ دانا زہوش
بہ چشم از نگاہ و بہ آہو ز رم
بہ چنگ از نوائے و بہ مطرب زدم
بہ باغ از بہار و بہ شاہ از نگیں
بہ گیسو زپیچ و بہ ابرو زچیں
عیار وجود آشکاراکنی
نشاں ہائے وجود آشکاراکنی
یہاں شاعر کی فکرکی روپھر مرکزکی طرف پلٹتی ہے اور وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے،
چہ باشد چنیں عالم آرائیے
ہمانا خیالے و تنہائیے
حسن ازل اپنی اس عینیت اور احدیت کے احساس سے جب اکتاتا ہے تواپنی خلاق قوت کوکام میں لاتا ہے اور اس عالم صورکوپیدا کرتاہے نہ صرف اس لئے کہ دوسرے اس کودیکھیں بلکہ اس لئے کہ وہ خودبھی اپنے کودیکھ سکے۔ یہ حسن ازل خودبین وخودنما بھی توہے۔
غالب اس فاطرعالم کوایک ایسی قوت سمجھتے ہیں جوسائرکائنات کے لئے سراپا وجودوکرم ہے اورتمام مخلوقات کی فلاح وبہبود ہروقت اس کے پیش نظر ہے اس لئے اس نے دکھ سے پہلے دکھ کی دواپیداکی۔
چارہ در سنگ و گیاہ و درد باجاں دار بود
پیش ازاں کیں دررسد آں رامہیا کردہ
اس منزل پرپہنچ کرشاعر چونکتا ہے اور اس کا شعور دوسری سطح پر آجاتاہے اور دوسرے زاویہ سے حقیقت اور مجازمعنی اورصورت ذات اورعکس ذات کے مسئلہ پرغور کرنے لگتا ہے۔ اس کے دل میں اندیشہ پیدا ہوتا ہے اوریہ اندیشہ اس کوپریشان کرنے لگتاہے۔ کیاعوام الناس تمام تربیت اورسعی وریاضت کے بعدبھی تخیل اور فکر کی اس طرح پر پہنچ سکتے ہیں کہ وہ ’’شہودومشاہد ومشہود‘‘ یا نظر وناظر کوایک سمجھ سکیں اورہر ’’حجاب‘‘ کو ’’سازکاپردہ‘‘ تسلیم کریں جس کے بغیر ’’نواہائے راز‘‘ کاصورت پکڑنامحالات سے ہے اورشاعر کا دل گواہی دیتا ہے کہ اس نکتہ تک پہنچناعام انسانی ذہن کے بس کی بات نہیں۔ پھرچند برگزیدہ اکابر کی شخصی اشراقیت (PERSONAL ILIUMINISM) خلق خدا کے کیا کام آسکتی ہے۔
غالب باربار ہمارے ذہن نشین کراتے ہیں کہ،
قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اورجزو میں کل
کھیل لڑکوں کاہوا دیدہ بینا نہ ہوا
یا
عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہوجانا
درد کاحد سے گزرناہے دوا ہوجانا
یا
قطرہ دریامیں جو مل جائے تو دریا ہوجائے
کام اچھا ہے وہ جس کاکہ مال اچھائیے
لیکن خوب معلوم ہے کہ یہ منزل ماورا عام انسانی رسائی کے دائرہ سے باہر ہے اورخواص بھی جواس منزل تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں یہاں مستقل قیام نہیں کرسکتے۔ ان کودنیائے گردوبار میں واپس آناپڑتا ہے جوان کا فطری اور اصلی مقام ہے۔
اب غالب کودوسرا خطرط محسوس ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہوکہ لوگ مجاز کواصل حقیقت اورعکس ذات کوعین ذات سمجھ لیں اور صورت پرستی میں مبتلاہوجائیں۔ اسی لئے کبھی وہ عالم کو ’’تمام حلقہ دام خیال‘‘ تصورکرتے ہیں اور اس کو خواب میں بھی دیکھنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ کچھ اشعار اس سلسلے میں یادگارہیں اس لئے نہیں کہ وہ دنیا کی بے ثباتی اورناپائداری کا سبق دیتے ہیں بلکہ اس لئے کہ وہ شاعری کے اچھے نمونے ہیں۔
بازیچہ اطفال ہے دنیا مرے آگے
ہوتا ہے شب و روزتماشا مرے آگے
جزنام نہیں صورت عالم مجھے منظور
جزوہم نہیں ہستی آشیامرے آگے
*
ہر زہ ہے نغمہ و بم ہستی وعدم
لغو ہے آئینہ فرق جنوں وتمکیں
لاف دانش غلط ونفع عبادت معلوم
دردیک ساغر غفلت ہے چہ دنیا چہ دیں
مثل مضمون وفا بابدست تسلیم
صورت نقش قدم خاک بہ فرق تمکیں
اورایک مشہورفارسی غزل کے یہ اشعار،
دود سودائے تتق بست آسماں نامیدمش
دیدہ درخواب پریشاں زدجہاں نامیدمش
وہم خاکے ریخت درچشمم بیاباں دیدمش
قطرہ بگداخت بحرپیکراں نامیدمش
لیکن یہ غالب کے دل کی آواز نہیں معلوم ہوتی اوراس عنوان کے اشعار ان کے فارسی اوراردوکلام میں معدودے چندنکلتے ہیں۔
ایک بارپھر غالب ہوشیارہوتے ہیں اور وہ تیسری اورآخری سطح پر آکرتیسرے زاویہ سے ہستی پرغورکرتے ہیں۔ یہ سطح پر ان کی فکرکا مستقرالیٰ حین ہے۔ ان کی اصل قدر اسی طرح پر نمایاں ہوتی ہے اوران کی فکرونظر کی یکتائی اوران کی شاعری کی برتری اسی مقام سے ہے۔
غالب کل یاخالق یاماورائے کائنات کی سطح سے غورکرنے کے بعد یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاعر کی اصل دنیا ’’یکتائی معشوق‘‘ کی نرگن دنیا نہیں ہے بلکہ جلوہ معشوق یعنی مظاہرہ وحوادث کی نیرنگیوں کی دنیاہے۔ انسان اورایک انسان ہونے کی حیثیت سے شاعرکاواسطہ خلق یاموجودات سے ہے جوسرتا ’’عالم فردانیت‘‘ ہے۔ اس عالم سے باہرانسان سیرتوکرسکتا ہے مگروہاں مستقل قیام نہیں کرسکتا۔ عالم خلق یا عالم موجودات میں ہرمخلوق اپنے انفرادی وجود کے زاویہ سے نظام ہستی کودیکھتا ہے اوراپنی فردیت کی جداگانہ حقیقت کوتسلیم کئے جانے کامطالبہ کرتاہے۔ کل کاوجودمسلم۔ لیکن اجزا کی الگ الگ حقیقت کوتسلیم کئے بغیرکل کا وجود محض واہمہ ہوگا اورہرجزوکی خیریت کی ضمانت کے بغیرکل کی خیریت محالات سے ہے۔
ہستی من حیث الکل سراپاخیروبرکت سہی لیکن جب ایک ایک فردمن حیث الفرد اپنے وجودپر نظرڈالتاہے تووہ ناگزیر طورپرفساد وفنا کی طرف رواں معلوم ہوتاہے اور زندگی اپنی فطرت ہی سے المیہ نظرآتی ہے۔ یہ احساس انسان میں کرب کی حد تک شدیدہوجاتاہے اس لئے کہ انسان میں شعور درجہ تکمیل پہنچ کاہے۔ شعورکی یہ شدت انسان کا سب سے بڑا امتیاز ہے مگریہی اس کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ نظام کائنات ہمیشہ سے ہے اورہمیشہ رہے گا مگر وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ہستی کے اجزاجزوی حیثیت سے مٹتے رہتے ہیں، نوع ہمیشہ باقی رہتی ہے مگر نوع کے افرادفناہوتے رہتے ہیں۔ انگریزی کے مشہور روزگارشاعرلارڈٹینی سن کے دل میں یہی خلش تھی جب اس نے اپنے شاہ کار مرثیہ ’’بیادگار‘‘ (IN MEMORIAM) میں یہ سوال کیا۔
’’کیا خدا اور قدرت برسرپیکارہیں
کہ قدرت ایسے فاسدخواب دکھاتی ہے
وہ (قدرت) نوع کی کتنی حفاطت کرتی ہے
(لیکن) فردواحد کی زندگی کی طرف سے کتنی بے پروا ہے‘‘
اوراب غالب کی طرف آئیے۔ وہ بھی جب افراد کی قدروغایت پرغورکرتے ہیں تو ان کوسارا نظام ہستی ایک مشق لام الف یا مرگ ونیستی کا کھیل معلوم ہوتا ہے اوران کی زبان سے بے اختیار نکل جاتاہے۔
نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا
کاغذی ہے پیرہن ہرپیکر تصویرکا
اس تاثر کو زیادہ عام فہم زبان میں پھریوں بیان کرتے ہیں۔
تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا
اڑنے سے پیشتر بھی مرا رنگ زردتھا
اوراسی شعور کے تحت وہ سوال کرتے ہیں اور یہ سوال ہی اپنا جواب بھی ہے۔
درخور قہروغضب جب کوئی ہم سا نہ ہوا
پھر غلط کیاہے کہ ہم سا کوئی پیدا نہ ہوا
انسان کے لئے یہ بڑا کرب ناک احساس ہے۔ غالب فطرتا ایک مفکرتھے وہ ہسی کے اس المیہ کی حکیمانہ تعبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
مری تعمیر میں مضمر ہے اک صورت خرابی کی
ہیولیٰ برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا
غالب آفرینش اورآفریدگارکی حقیقت سے اچھی طرح آگاہ ہیں۔ وہ عالم اورماورائے عالم دونوں کے عارف ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنی فکر ونظر کو بیشتر انسان اورانسانیت کے لئے وقف کئے ہوئے ہیں۔ وہ انسانی دنیا اور انسانی فطرت کے رموز ومسائل کے شاعرہیں۔ ان کاپیغام انسانیت ہے۔ وہ آدمی ہونا اورآدمی رہناسکھاتے ہیں۔ وہ ہم کو آگاہ کرتے ہیں کہ آدمی کا انسان ہوناآسان نہیں ہے یعنی اگرآدمی انسان ہوجائے تویہ اس کا بہت بڑا اکتساب ہوگا۔
غالب نہ ملکوت ولاہوت میں محوہوئے نہ انہوں نے کبھی ’’فوق البشر‘‘ کاخواب دیکھا۔ انہوں نے صرف انسان پر غورکیا جو شعورکامکمل نمونہ ہے۔ یہی شعور انسان کاالمیہ بھی ہے اوریہی اس کی خیروبرکت اور اس کی نجات کاضامن بھی۔
غالب کو شدیداحساس ہے کہ انسان ایک مجبور اور بے بس مخلوق ہے جس کواپنے آغاز وانجام پر کوئی اختیارنہیں اس بے بسی اوربے چارگی کی بھی کوئی انتہاہے۔
رومیں ہے رخش عم کہاں دیکھئے تھمے
نے ہاتھ باگ پر ہے نہ پاہے رکاب میں
یہ مجبوری اوردرماندگی انسان کی ہمزاد ہے۔ ایک جگہ استعارے میں غالب نے بڑے دلنشیں انداز سے اس صورت حال کوبیان کیاہے۔
پنہاں تھا دام سخت قریب آشیانے کے
اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے
ایک دوسراشعر ذرا دوسرے رخ سے اسی احساس مجبوری کی ترجمانی کرتا ہے اور استعارہ اگرچہ روایتی ہے لیکن شاعر نے اس میں جونئی روح پھونکی ہے وہ اسی کا حصہ ہے۔
مثال یہ مری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر
کرے قفس میں فراہم خس آشیاں کے لئے
زندگی کے ہرمیدان میں انسان کو قدم قدم پرمجبوریوں کا سامناکرناپڑتا ہے۔ غالب ایک شعر میں کسی قدر طنز کے ساتھ ہم کو احساس دلاتے ہیں۔
مجبوری و دعوائے گرفتارئی الفت
دست تہ سنگ آمدہ پیمان وفا ہے
لیکن غالب ہم کوقنوطیت کادرس نہیں دیتے۔ ہم مغلوب ومجبو ر سہی لیکن مغلوبیت فطرت انسانی کے ناموس پرایک بدنماداغ ہوگا۔ ہماری آرزوئیں پوری نہیں ہوتیں۔ ہماری امیدیں ٹوٹتی رہتی ہیں لیکن اس سے ولولہ زندگی اور نشاط کار میں کمی نہیں ہونی چاہئے۔ ٹھیک ہے۔ مرناہمارا مقصد ہے۔ مگرمرنے سے پہلے سرپرہاتھ دھرکے بیٹھے رہنا نامردی ہے۔ ہم کوشکست پرشکست کے باوجود شکست پرقابوپانے کے لئے جدوجہد کرتے رہنا ہے اور چونکہ ناگزیر ہے اس کے لئے اوربھی زیادہ انہماک کے ساتھ ہم کواپنے مقصد پرفتح پانے کے لئے حوصلہ اورمحت کے ساتھ کوشاں رہناہے۔
ہوس کوہے نشاط کار کیاکیا
نہ ہو مرناتو جینے کا مزا کیا
انسان کاخلقی منصب یہ ہے کہ وہ اپنی تمام محرومیوں اورمایوسیوں کے درمیان اپنے سینہ کو آرزو سے آباد رکھے اورامید کی شمع کوکسی حال میں گل نہ ہونے دے۔ یہ بھی اس کے مقدر ہی کا ایک جزوہے اور وہ طبیعی اورطبعی طورپر اس کے لئے مجبور ہے۔ اگرانسان اس طرح اپنے کوسنبھالے نہ رہے تو اس کے سامنے خودکشی کے سوا کوئی راستہ نہیں۔
نہ لائی شوخی اندیشہ تاب رنج نومیدی
کف افسوس ملنا عہد تجدید تمنا ہے
یااس شعر پرغورکیجئے۔ اگریہ غالب ہی کا شعرہے،
روائی کی نہ دی تقدیر نے مقصد کومنظوری
بہم رہنے لگے دونوں تمنا اورمجبوری
اسی لئے غالب ہم کویہ تعلیم دیتے ہیں،
نفس نہ انجمن آرزوئے سے باہرکھینچ
اگر شراب نہیں انتطار ساغر کھینچ
دوسرے استعاروں میں فطرت انسانی کے اس رازکو یوں سمجھا گیاہے۔
بلاسے ہیں جویہ پیش نظر درو دیوار
نگاہ شوق کو ہیں بال وپرد ر ودیوار
ایک شعر جوپہلے بھی سناچکاہو ں پھر سنئے اور اس کے مضمرات پرغورکیجئے۔ وہ غزل جس کاایک شعرسنایاجارہاے نسخہ ’’حمیدیہ‘‘ میں ہے۔
شکوہ وشکر کوثمربیم امید کاسمجھ
خانہ آگہی خراب دل نہ سمجھ بلاسمجھ
انسان کوجن خصوصیات نے اشرف المخلوقات بنایاہے وہی اس کے لئے ابتلاومصیبت کاموجب بھی ہیں اوران خصوصیات میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صاحب دل ہے اور جاندار بھی دل رکھتے ہیں لیکن ان کا دل صرف مضغہ گوشت ہے۔ انسان کادل ایک ناقابل تسخیر توانائی ہے اوراسی دل کی بدولت وہ قدرت کے عناصر و مطاہر کومسخر کرتاچلاآیاہے۔ جب تک اس کے سینے میں یہ دل ہے وہ بیم ورجا کی کشمکش میں مبتلا رہے گا۔ یعنی اس دل کا دوسرا نام بلام ہے جولوگ اس حقیقت کونہیں سمجھتے یا اس سے روگردانی کرتے ہیں ان کوغالب ’’خانہ آگہی خراب‘‘ تصورکرتے ہیں۔ نظیری کابھی ایک شعر ہے جوان کے اپنے مزاج اورانداز بیان کی چھاپ لئے ہوئے ہے۔
بغیردل ہمہ نقش ونگار بے معنی است
ہمیں ورق کہ سیہ گشت مدعا ایں جاست
غالب ناامیدی کوانسان کے حق میں ایک مہلک خطرہ سمجھتے ہیں اور اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ ناامیدی نیستی کی طرف لے جاتی ہے۔ ان کی ایک مشہور غزل کاایک شعر ہے جوفکروفن کے معجزات میں سے ہے۔
بس ہجوم ناامیدی خاک میں مل جائے گی
یہ جواک لذت ہماری سعی بے حاصل میں ہے
آدمی کا فطری منصب محنت وکاوش اورسعی وپیکار ہے اورسعی وپیکار خوداپنی جگہ ایک مقصد اورایک قدر ہے۔ اس لئے اس کے باحاصل یا بے حاصل ہونے کا دراصل سوال نہیں اٹھتا۔ اگرآرزو کاانجام شکست آرزو ہے تویہ شکست آرزوہی ہماری آرزوبھی ہے۔ آرزوئے پیہم ہی ہماری زندگی میں کیف ولذت کا سبب ہے۔
طبع ہے مشتاق لذتہائے حسرت کیا کروں
آرزوسے ہے شکست آرزو مطلب مجھے
اسی قبیل کا ایک اورشعر یاد آگیا۔
عشرت پارۂ دل زخم تمنا کھانا
لذت ریش جگر غرق نمک داں ہونا
ہزارآسودگیوں اورناآسودگیوں کے بعدبھی تمناانسان کی طبیعت کوچین نہیں لینے دیتے۔ اس نکتہ کوکتنی دلنشینی کے ساتھ اس شعر میں بیان کیاگیاہے۔
ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہرخواہش پہ نکلے
بہت نکلے مرے ارمان لیکن پھر بھی کم نہیں
آرزومندی ایک ادنی وجود کوکہاں سے کہاں پہنچاسکتی ہے۔ اس کو غالب کی زبان میں سنئے،
شوق ہے ساماں طراز نازش ارباب عجز
ذرہ صحرا دست گاہ و قطرہ دریا آشنا
وجودانسانی کی اس حقیقت کوسمجھنے اور سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لئے بڑے جگرکی ضرورت ہے۔ غالب ایسی ہی ’’جگرداری‘‘ کی تلقین کرتے ہیں اور اس کے لئے مردہونے کی ضرورت ہے۔ غالب کا محاورہ میں آدمیت کی پہچان مردانگی ہے۔ زندگی ایک مبارزہ ہے جس سے مردہی عہدہ برآہوسکتاہے۔
دھمکی میں مرگیا جونہ باب نبردتھا
عشق نبردپیشہ طلب گار مرد تھا
اورمرد کی پہچان کیاہے۔ غالب نے اپنی پہلی فارسی مثنوی موسوم بہ ’’سرمہ بینش‘‘ میں امن کی طرف بڑے بلیغ اشارے کئے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ مثنوی میں مرد کے سارے اوصاف بہادرشاہ ظفرمیں مرکوزدکھائے گئے ہیں لیکن یہ وقت اورحالات کا تقاضاتھا۔ مرد کی تعریف میں جوچنداشعار کئے گئے ہیں وہ مثنوی کی جان ہیں اورکلیات کاحکم رکھتے ہیں۔
مردکی تعریف ہمیشہ وہی رہے گی جوان اشعار میں کئی گئی ہے۔
گرنہ دل ریش ازمستی ملاف
کیں مے ازتندی بود پہلوشگاف
ا ے کہ از راز نہاں آگہ نہ
دم مزن از رہ کہ مرد رہ نہ
مرد رہ باید کہ باشد مردعشق
لب ترنم خیز و دردل ورد عشق
میرا دعوی ہے کہ انسانی تہذیب کی تاریخ کے کسی دور میں کوئی ملک کوئی قوم ’’مرد‘‘ کااس سے رفیع ترتصور نہیں پیش کرسکی ہے اورآج بھی ’’مرد‘‘ کا اس سے زیادہ بلندمعیار کسی خطہ اورکسی زبان میں نہیں ملے گا۔
غالب نے انسانیت کے مقام سے انسانی زندگی کاکون ساپہلو ہے یا ان کاکون سا مسئلہ یامعاملہ ہے جس پر اپنے منفرد اندازمیں اظہار خیال کرکے ہمارے اندرنئی بصیرت نہ پیدا کی ہو اورہم کوبہتر انسان بنانے کی کوشش نہ کی ہو۔ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری نے اپنا دائرہ اردو دیوان غالب تک محدود رکھتے ہوئے کہا تھا کہ ’’لوح سے تحت تک مشکل سے سوصفحے ہیں لیکن کیا ہے جو یہاں حاضرنہیں۔ کون سا نغمہ ہے جو اس ساززندگی کے تاروں میں بیداریاخوابیدہ موجودنہیں ہے۔‘‘ یہ حکم غالب کی ساری شاعری کے بارے میں صحیح ہے وہ اردوہویافارسی۔ آئیے کچھ اشعار پرتجزیاتی نظرڈالی جائے۔
سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ غالب خداکے قائل تھے۔ رسول اورآل رسول سے ان کوسچی خراج عقیدت تھی۔ حضرت علی کووہ بطل مانتے تھے اوران کے ساتھ والہانہ گرویدگی رکھتے تھے۔ شرح محمدی کے وہ قائل تھے اوراس کے خلاف زندگی بسر کرنے کو وہ دونوں جہان کی روسیاہی تصور کرتے تھے۔ وہ خوداپنی وضع زندگی کوگناہ سمجھتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کی سی زندگی بسرکرے۔ مختصریہ کہ وہ دین اسلام کوخداکاآخری پیغام سمجھتے تھے اور اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرناان کے نزدیک فلاح دارین کاذریعہ تھا لیکن وہ ظاہر پرستی کے دشمن تھے اوررسوم وقیود میں غلوکوکسی طرح گوارانہیں کرسکتے تھے۔ رواج پرست اور دکھانے کے لئے روزہ رکھنے والے دن بھر جس طرح افطار کے اہتمام میں لگتے رہتے ہیں اورغروب آفتاب کا جس لگن کے ساتھ انتطار کرتے ہیں اس پرغالب نے فارسی کے ایک شعر میں کس بلاغت کے ساتھ افسوس کااظہار کیاہے۔
تن پروری خلق فزوں شدز ریاضت
جز گرمئی افطار نہ دارد رمضان ہیچ
فقہادین کاجوتصور پیش کرتے رہے ہیں اور مذہبی زندگی کا جونصاب انہوں نے بنارکھا ہے وہ ایک قسم کی سوداگری ہے جوخداپرستی کی روح کومجروح کرتی ہے۔ علمائے دین اورہادیان شرع متین جس طول کلام سے کام لیتے ہیں اورجس ظاہردارانہ دستور زندگی کی وہ تبلیغ کرتے ہیں وہ ریاکاری ہے اور اس اسلام سے اس کاکوئی واسطہ نہیں جودین فطرت ہے۔ غالب ملائیت یامذہب کی اجارہ داری کے سخت مخالف تھے۔ سنجیدگی کے ساتھ بھی اورمزاجیہ لہجہ میں بھی۔ انہوں نے بار بار ایمان کے تاجروں سے ہوشیاررہنے کی تلقین کی ہے۔ ایک فارسی شعر میں کہتے ہیں۔
تکیہ برعالم دعابدتنواں کرد کہ ہست
ایں یکے بہیدہ گوداں دگرے بہیدہ کوش
یہ پوری غزل ایک ذہنی عالم میں کہی گئی اوران لوگوں سے خبردار رہنے کی مسلسل تلقین ہے جوصرف رسوم وظواہر کوعبادت سمجھتے ہیں اوراسی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ غالب عبادت کے دل سے قائل تھے چاہے خودصوم صلوۃ کاحق ادا کرسکے ہوں لیکن ایک بات سے ان کوسخت نفرت تھی اور وہ تھی عبادت کے پردے میں۔ ریاکاری اورذاتی کام جوئی۔ اردوکے یہ دوشعر غالب کے اصلی عقیدہ کی نمائندگی کرتے ہیں اورہمارے لئے قابل غور ہیں۔
طاعت میں تار ہے نہ مئے وانبگیں کی لاگ
دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کربہشت کو
کیا زہد کو مانوں کہ نہ ہوگرچہ ریائی
پاداش عمل کی طمع خام بہت ہے
ایک جگہ کس عارفانہ شوخی کے ساتھ کہتے ہیں،
واعظ نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو
کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی
غالب کی ساری کافرماجرائیاں انہیں ظاہر پرست اوررسوم نوازدین کی برکتیں تقسیم کرنے والوں کے خلاف مجاہدہ ہیں۔ وہ خود ایک شعر میں بہت صاف کہتے ہیں۔
سخن کو تہہ مراہم دل بہ تقوی مائل استہا
زننگ زاہد افتادم بہ کافر ماجرائیہا
غالب عملی طورپر احکام شرع کے پابندنہ سہی، مگر وہ اپنے دین کے اصول وامور کے دل سے معترف تھے اوراپنے عقائد میں راسخ تھے۔ اس کے باوجود وہ بے انتہا کشادہ دل اوروسیع النظر انسان تھے اوران کی ان انسانیت کا یہ تقاضا تھا کہ اگر دوسروں کودوسرے عقائد میں خلوص اور استحکام کے ساتھ ویسا ہی شغف اور انہماک ہے توہم کوان کا احترام کرناچاہئے۔ دراصل ہم کوتو یہ دیکھنا ہے کہ کون اپنے دین کی میزان پرکس حد تک پورا اترتاہے۔ غالب کھلے ہوئے الفاظ میں ایک جگہ کہتے ہیں۔
نہیں کچھ سجدوزنار کے پھندے میں گیرائی
وفاداری میں یہ شیخ وبرہمن کی آزمائش ہے
اور اس شعر کا توکوئی جواب نہیں جوضرب المثل ہوچکاہے۔
وفاداری بہ شرط استواری اصل ایماں ہے
مرے بت خانہ میں توکعبہ میں گاڑوبرہمن کو
دنیا میں بڑاشاعر وہی مانا گیاہے اور تاریخ میں وہی اپنی ساکھ قائم کرسکا ہے جس کے کلام نے انسان کی فطرت کوملحوظ رکھتے ہوئے اس کوپہلے سے بہترانسان بنانے میں کوئی اہم حصہ لیاہو۔ غالب کا شمار بھی ایسے ہی بڑے اور تاریخی منزلت رکھنے والے شاعروں میں ہوگا۔ ان کے اردودیوان اورفارسی کلیات میں ایسے اشعار بکھرے پڑے ہیں۔ نہ جانے کتنے ہی اشعارایسے ہیں جوآداب اخلاق ومعاشرت کا تخیلی نصاب بن سکتے ہیں۔ چنداشعار کسی اہتمام کے بغیرصرف اپنی یاد سے منتخب کئے گئے ہیں جو پیش کئے جائیں گے۔ لیکن آپ خودمحسوس کریں گے کہ غالب کی کہی ہوئی باتوں میں نہ واعظ یاناصح کے پندونصیحت کی تلخی ہے نہ مدرس کے دیئے ہوئے سبق کی بے کیفی۔ جن دواشعار میں مجھے سب سے زیادہ نثریت محسوس ہوئی ان کو سب سے پہلے ہی سنادیتا ہوں۔
نہ سنوگرا کہے کوئی نہ کہو گر برا کرے کوئی
روک دو گر غلط چلے کوئی بخش دو گر خطا کرے کوئی
ان میں بھی غالب کے لہجہ کی قطعیت موجود ہے اوراگرکوئی ان کواپنی زندگی کادستور بنائے تواس کی شرافت نفس کا معیاربہت بلندتصور کیاجائے گا۔
شاعری میں دیوانگی وحشت مجذوبیت جیسی ذہنی غرابتوں کومعاملات روحانی میں شمارکیاگیاہے اورزندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ہوش وخرد دیوانوں اورمجذوبوں کے لئے ربط اوربے قاعدہ قول وفعل کونہ صرف برداشت کرتے ہیں بلکہ ان سے مرعوب بھی رہتے ہیں۔ غالب وحشت اوردیوانگی میں بھی ایک ضابطہ چاہتے ہیں۔ ان کاخیال ہے کہ دیوانگی اگرکوئی اکتساب یاکمال ہے تواپنے لئے ہے اور اس کواپنی ذات تک محدود رکھناچاہئے۔ ہم کوکوئی حق نہیں کہ ہم اپنی دیوانگی کااظہار سربازاریا مجلسوں میں کرتے پھریں۔ مجلسی آداب کااحساس بہرحال لازم ہے۔ یہ شعر اس قابل ہے کہ اس پرغورکیاجائے اوراس کویاد رکھاجائے۔
وارفتگی بہانہ بیگانگی نہیں
اپنے سے کہ نہ غیر سے وحشت ہی کیوں نہ ہو
اسی غزل کاایک اورشعرہے جس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ کسی کا احسان لینا ہماری ہمت کوپست کرتاہے اورہمارے کردارکو بگاڑتاہے۔
ہنگامہ زبونی ہمت ہے انفعال
حاصل نہ کیجئے دھر سے عبرت ہی کیوں نہ ہو
اسی مضمون کودوسری غزل کے ایک شعر میں یوں ادا کیاگیاہے۔
دلوار بارمنت مزدور سے ہے خم
اے خانماں خراب نہ احسان اٹھائے
یعنی مزدور کا احسان لینے سے خانماں برباد رہنابہترہے۔
دنیا میں کون ہے جس کوکوئی نہ کوئی حاجت نہ ہو۔ ادنی ہویااعلیٰ کسی کی زندگی اس کلیے سے مستثنیٰ نہیں .....ہم سب اس حقیقت کوجانتے ہیں اورغیرارادی اوربے مقصد طورپرزبان سے اس کا اظہار بھی کیاکرتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں اور میکانکی اندازمیں کہا کرتے ہیں کہ کوئی کس کس کی حاجت پوری کرسکتاہے اورکہاں تک۔ اب غالب کے اس شعر پرغورکیجئے۔
کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند
کس کی حاجت روا کرے کوئی
بہ ظاہر غالب کی کہی ہوئی بات سطحی اورعامیانہ معلوم ہوگی لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس سے ہمارے بے جان یانیم جان شعور میں زندگی کانیا اہتراز پیداہوتاہے۔ شاعر کے لہجہ میں جوپترتامل گذار ہے اس کے استفسار میں جودانش ورانہ درد مندی اس سے ہم کوایک نئی بصیرت ملتی ہے جوہم کو اس قابل بناتی ہے کہ ہم معاشرہ کی اس کلی اورعمومی حقیقت کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھ سکیں اور اگر اس کا کوئی تدارک ممکن نہیں تو خاموش رہیں۔ یہ خاموشی جھوٹی یا مجہول ہمدردی یا ریاکارانہ ترس سے زیادہ جلیل ہے۔
اس سلسلے میں اب ایک اورشعر ملاحظہ ہو جس میں یہ بتایا گیاہے کہ صاحب حاجت کوکیا روش اختیارکرناچاہئے تاکہ اس کے انسانی ناموس کی سالمیت اور وقعت مجروح نہ ہونے پائے۔
بے طلب دیں تو مزہ اس میں سواملتاہے
وہ گدا جس کونہ ہوخوئے سوال اچھا ہے
غالب سے پہلے کبیرداس بھی ہم کویہی تعلیم دے گئے ہیں۔ ان کی ایک رمینی ہے جو ضرب المثل ہوچکی ہے۔
بن مانگے سو دودھ برابرمانگے ملے سویانی
کہیں کبیر وہ رکتی برابر جا میں اینچا تانی
جومانگے بغیروہ دودھ جومانگے سے ملے وہ پانی ہے یعنی بے مزہ ہے اورجوجھگڑے فساد سے ملے وہ خون کے برابر ہے۔ اورحضرت ابوہریرہ کی روایت سے نبی اکرم کی حدیث ہے۔ والذی نفسی بیدہ لان یاخذاحکم حبلۃ فیعتطب علی ظہرہ خیرکم من ان یاتی رجلا فیسئالہ اعطاہ اوضعہ۔ یعنی اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں سے جو شخص ہاتھ میں رسی لے اور اپنی پیٹھ پرلکڑیوں کاگٹھا لادے اس کایہ کام اس سے زیادہ نیک ہے کہ وہ کسی شخص سے سوال کرے اوروہ اس کوکچھ دے دے یا انکار کردے۔ مگر جب خود غالب کو ’’اہل کرم‘‘ کا تماشہ دیکھنا اور ان کی پراحتیال طبیعت کا مطالعہ کرنا ہوتاہے تو وہ فقیروں ہی کابھیس بناکر نکلتے ہیں۔
غالب کی شاعری بہ یک وقت ہمارے دل اوردماغ دونوں کوآسودہ کرتی ہے وہ ہمارے احساس وفکر کونئے انداز سے چھیڑکرچونکاتے ہیں اورنئی روشنی میں نئے پہلوؤں اورزاویوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ دلی واردات اور ذہنی کیفیات کو صرف بیان کرکے نہیں رہ جاتے بلکہ ان پر استفسار اورتامل کی تلقین کرتے ہیں۔ غالب کی اصلی بزرگی یہ ہے کہ وہ تخلیق کائنات کے مابعدالطبعیاتی حقائق کی معرفت رکھتے ہوئے ارضی اور انسانی زندگی اوراس زندگی کے ہرپہلو اورہر سطح کے شاعر ہیں۔ وہ اس راز سے واقف ہیں کہ حقیقت کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں اور وہ کئی پہلو رکھتی ہے جوایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں مگرباہم ایک مکمل آہنگ ہوتے ہیں۔ غالب کے کلیات نظم (اردووفارسی میں) ایسے اشعار کی کمی نہیں جو بظاہر مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے کی تردید کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں لیکن دراصل ایسانہیں ہے۔ مثال کے طورپر فرہادشیریں اورخسرو کی تلمیحات سے کام لے کر شاعر نے انسان کی زندگی کے ایک ناگزیرمیلان یعنی عشق سے متعلق کچھ نکتے ہم کوسمجھائے ہیں جوقابل غورہیں۔ غالب فرہاد کی عظمت کے قائل ہیں۔ بدویت سے دورحاضر تک نفس انسانی کی تہذیب میں عشق نے جوحصہ لیاہے اس کی ایک اور تاریخ ہے اور اس تاریخ میں فرہاد ایک ممتازمرتبہ رکھتاہے جو قابل رشک ہے۔ عشق کی راہ میں فرہاد کی سعی وکاوش کااعتراف واحترام کرتے ہوئے غالب کہتے ہیں:۔
کیست کز کوشش فرہاد نشاں باز دھد
مگر آں نقش کہ از تیشہ بہ خارا ماند
اورپھرایک دوسرے شعر میں کس ولولہ اورفخر کے ساتھ کہتے ہیں،
از رشک بہ خون غلتم و از ذوق برقصم
زاں تیشہ کہ درپنجہ فرہاد بہ جنبد
ایک جگہ آشفتہ بران عشق کی جماعت کی طرف سے فرہاد کی وکالت ان الفاظ میں کرتے ہیں،
پیشہ میں عیب نہیں رکھئے نہ فرہاد کونام
ہمیں آشفتہ سروں میں وہ جواں میربھی تھا
لیکن معاً غالب کی ہمہ سمتی نگاہ فرہاد کی زندگی کے دوسرے زایوں پرپڑتی ہے اور وہ اپنی طبعی صداقت پرستی سے مجبورہوکر فرہاد کے خلاف فتوی صادر فرمانے میں درنگ کوراہ نہیں دیتے۔ سب سے پہلی بات جوفرہاد کے کردار میں کھٹکتی ہے وہ اس کا روایات پارینہ کاپابند ہونا ہے ورنہ فطرتا عشق توآزاد ہوتاہے۔ اس کوروایت پرستی سے کیاواسطہ۔ اسی لئے غالب کچھ مایوسی کے ساتھ کہتے ہیں،
تیشہ بغیر مر نہ سکا کوہ کن اسد
سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا
عشق کا اپنا ایک ناموس ہے اور اس کی اپنی ایک شریعت ہے۔ مروجہ شرع وآئین اوررسوم وقیوداس پرعائد نہیں کئے جاسکتے۔ ایسے مقبول انام رسمی قاعدوں اورطریقوں سے عاشق محبوب کونہیں پاسکتا اور اس کی دلی مراد کبھی پوری نہیں ہوسکتی۔ غالب ’’کوشش فرہاد‘‘ کے ایک نئے روح کوہمارے سامنے لاکرعشق کی فطرت آزاد کا احساس دلاتے ہیں۔
کوہ کن نقاش یک تمثال شیریں تھا اسد
سنگ سے سرمارکر ہووے نہ پیدا آشنا
یہ شعر اس بات کی بھی شہادت ہے کہ ایران کے اساطیر وتواریخ اوراس کے ادبی اورتہذیبی روایات ومنقولات پر غالب کو کتنا عبورحاصل تھا۔ شیریں اور فرہاد کی داستان سے شغف رکھنے والوں میں شاید ہی کوئی اس روایت سے واقف ہو کہ جب فرہاد شیریں کی شرط کے مطابق پہاڑ کاٹ کرچٹانیں نیچے دریا اکشارت یادریائے سیحون میں گرانے لگاتا کہ دریا کا رخ بنجرزمین کی طرف موڑسکے تواس نے اپنی تقویت اور تسکین کے لئے پہاڑ پر اپنی نظر کے سامنے ایک جگہ صاف کر کے شیریں کا ایک نقش بنالیاتھا۔ جب تھک جاتاتھا تو اس نقش کو دیکھ کر تازہ دم ہوجاتاتھا اورپھر نئی امنگ کے ساتھ پہاڑ کاٹنے میں منہمک ہوجاتاتھا۔
لیکن غالب کی طبیعت جس بات کوکسی طرح قبول نہیں کرسکتی وہ یہ ہے کہ فرہاد وصل کی آرزو سے اس قدر بے قابوہوگیاکہ وہ قصر شیریں تک پہاڑ کاٹ کرنہر جاری کرنے کے لئے تیارہوگیا اوریہ نہ سوچا کہ یہ تورقیب کی جوایک جابرشہنشاہ ہے مزدور ی کرناہے اوراسی کے لئے عیش ونشاط مہیا کرناہے۔ مندرجہ ذیل دواشعار میں غالب اپنے اسی تاثر کااظہار کرتے ہیں۔
کوہ کن ومزدوری عشرت گہ خسروکیا خوب
ہم کوتسلیم نکونامئی فرہاد نہیں
کوہ کن گرسنہ مزدور طرب گاہ رقیب
بے ستوں آئینہ خواب گران شیریں
یہاں غالب نے فرہاد، شیریں اور پرویزکی اس داستان کوتسلیم کرلیاہے جو فارسی مثنوی نگاروں کے ذریعہ مقبول اوررائج ہوگئی تھی اورجواصل داستان سے بالکل مختلف ہے۔
غالب کی نظر میں انسان کا درجہ ایک مخلوق کی حیثیت سے بہت بلند ہے اورانسانیت ایک بہت بڑی فضیلت ہے جس کو برقراررکھنامشکل ہے۔
آدمی کوبھی میسر نہیں انساں ہونا
اورغالب بتاچکے ہیں کہ آدمی یاانسان کاامتیازی نشان مردانگی یافتوت ہے۔ اگرانسان مرداورقابل نبردنہیں ہے تووہ کچھ نہیں ہے اور مردکی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں عشق کا درد رکھتاہو اوریہ درد عشق ہونٹوں سے ایک ولولہ انگیز ترنم کی شکل میں ظاہر ہو۔ انسانی ہستی اورعشق غالب کے تصور میں ایک ہی قوت کے دونام ہیں۔ عشق ایک فعال اور خلاق قوت ہے جس کوجوہراوّل کتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ کہیں کہیں غالب نے عشق کا وہ تصورپیش کیاہے جس سے عوام آشنا اورمانوس ہیں۔ مثلاً:۔
عشق نے غالب نکما کردیا
ورنہ ہم بھی آدمی کام کے
عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ ٓتش غالب
کہ لگائے نہ لگے اوربجھائے نہ بنے
مگریہ اس لئے ہے کہ جیسا کہ پہلے اصرر کے ساتھ کہہ چکاہوں غالب زندگی کی ہرسطح کے شاعرتھے۔ ورنہ ان کے نظام فکر میں عشق کا تصور تصوف کے ابہام کے بغیرحکیمانہ تھا اور اس کا وہی مقام ہے جوبیرگستان کے وہاں ’’قوت حیاتیہ’‘ (ELAN VITAL) یارودلف آئیلن کے وہاں آزاد اور روحانی حرکت (INDEPENDENT SPIRITUAL PROCESS) کا ہے۔ یعنی غالب کے ذہن میں عشق اورزندگی باہم مترادف ہیں۔ وہ جنسی تحریک جس کو عام زبان میں عشق کہا جاتا ہے وہ بھی عشق کاایک روپ ہے۔ عشق ایک آزاد تخلیقی قوت ہے اوراس کا پہلا مطالبہ ایثار اورقربانی ہے۔ مجبوری اوراپنی ہستی کی سلامتی کی فکرکاعشق کے ساتھ گزرنہیں۔ خواجہ حسن دہلو ی کا ایک شعرہے۔
حسن از عشق می ورزی چنیں از جاں چہ می لرزی
بہ یک دل درنمی گنجد غم جان وغم جاناں
اسی خیال کو غالب اپنے انداز میں اداکرتے ہیں۔
سراپا رہن عشق وناگزیر الفت ہستی
عبادت برق کی کرتا ہوں اورافسوس حاصل کا
یعنی اگرخرمن ہستی کی خیرمناناہے تو عشق کے قریب نہ جاؤ۔ عشق توایک بجلی ہے اوراپنے پرستاروں سے ساری ہستی کی بھینٹ چاہتاہے۔
اس سے پہلے بھی ایک شعر سنایاجاچکاہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ پیمان وفا کے ہاتھ کاآزاد ہونا لازمی ہے۔ اگرزندگی کی ادنی اورکثیف مجبوریوں سے آزاد اوربے نیاز نہیں ہوسکتے تومحبت اوروفا کا نام نہ لو۔
غالب کی ایک بہت بڑی دین جرأت اظہار ہے چاہے خدا کے سا منے ہو چاہے معشوق کے سامنے وہ انتہائی بیباکی کے ساتھ حق بات کہہ دیتے ہیں اورخدا کی روبرو بندے اور معشوق کے روبروعاشق کا وقارقائم رکھتے ہیں، لیکن ان کی جرأت اوربیبیاکی میں تہذیب اور شائستگی کی تہہ درتہہ نزاکتیں ہوتی ہیں۔ بعدکی نسلوں نے کیا شاعری میں کیا نثرمیں جہاں غالب سے اوربہت کچھ سیکھا ہے وہاں اظہار کا، یہ راست بازانہ اورجرأت مندانہ سلیقہ بھی سیکھا ہے۔
غالب کے کلام سے ان عنوان کی چند مثالوں پر غورکیجئے جواپنی ایک منفرد شان کی حامل ہیں۔ ایسے میلان فکر اور ایسے طرزبیان کے نمونے غالب سے پہلے یا خود ان کے عہد میں یاعرصہ تک ان کے بعد بھی کسی اردویافارسی کے شاعر کے کلیات میں نایاب ہیں۔
پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پرناحق
آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا
ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد
یارب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے
آتا ہے داغ حسرت دل کا شماریاد
مجھ سے مرے گنہ کا حساب اے خدا نہ مانگ
شاید ہی کوئی صاحب ادراک ایسا ہو جس کے دل میں کبھی نہ کبھی اس قسم کے احساسات یا خیالات خلش نہ پیدا کرتے ہوں لیکن ایسے کتنے ہوں گے جوزبان سے اظہار کی جرأت کرسکیں یا جواس تربیت یافتہ منطقی لہجہ میں اظہار کی قابلیت رکھتے ہوں۔ بیباکی، شوخی، گستاخی، ظرافت اورطنز کے بھی کچھ آداب وضوابط ہوتے ہیں۔ جس احساس کا آخری دوشعروں میں اظہار کیاگیاہے۔ معلوم ہوتا ہے وہ غالب کے شاعرانہ تخیل کی کوئی وقتی اپج نہیں ہے بلکہ ان کے دل کی ایک مستقل آواز ہے۔ ایک فارسی شعر میں بھی وہ اس احساس حرماں کویوں بیان کرتے ہیں۔
اندراں روز کہ پرسش روداز ہرچہ گذشت
کاش باماسخن از حسرت مانیز کنند
اورغالب کے حوصلہ گناہ اورحسرت عصیاں کااندازہ اس شعر سے کیجئے۔
دریائے معاصی تنک آبی سے ہوا خشک
میرا سردامن بھی ابھی تر نہ ہوا تھا
لیکن غالب کے حوصلہ زندگی اور ان کے بیباک مواجہہ اورمخاطبہ کی بہترین مثال ان کی طویل مثنوی ’’ابرگہربار’‘ میں ملتی ہے جو مثنویات میں شاہکار ہے۔ غالب ایک شعر میں کہہ چکے ہیں،
زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب
ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے
اب مثنوی ’’ابرگہربار‘‘ کے کچھ منتخب اشعار پیش کئے جاتے ہیں جن سے ہم یہ سبق ملتاہے کہ تربیت یافتہ انداز کلام اورشائستہ سلیقہ گفتگو کس کوکہتے ہیں۔ خدا کی شان خدائی۔ اس کی قدرت مطلق اورجزووکل میں اس کی مشیت کی کارفرمائی کا بیان ایک ایسی حمد ہے جس کی نظیر مشکل ہی سے کہیں ملے گی۔ یہاں بھی شاعر کے منفردانداز کا اعتراف کرنا پڑتاہے لیکن مثنوی کی روح وہ حصہ ہے جس میں داور محشر کے سامنے اعمال نیک وبدمیزان میں تولے جانے والے ہیں اورجزا وسزا کافیصلہ ہونے والا ہے۔ ذراسنئے غالب اپنے گناہوں کی معصومیت کا احساس قائم رکھتے ہوئے کس باوقار اورپراعتماد لہجہ میں اپنے مقدمہ کی خودوکالت کرتے ہیں۔
بروزے کہ مردم شوند انجمن
شود تازہ پیوند جان ہا بہ تن
بہ ہنگامہ با ایں جگر کوشہ گان
درآئینہ مشتے جگر توشہ گاں
زحسرت بہ دل بردہ دنداں فرو
زخجلت سراندرگریباں فرو
در آں حلقہ من باشم وسینہ
زغم ہائے ایام گنجینہ
در آب ودر آتش بسر بردہ
زد شواری زیستن مردہ
اپنے یہ حال بیان کرنے کے بعد ذرا سنئے مالک حشر سے درخواست کیا کرتے ہیں۔
بہ بخشائے برناکسی ہائے من
تہی دست ودرماندہ ام وائے من
بہ دوش ترازو منہ بارمن
نہ سنجیدہ بگزار کردارمن
بہ کردار سنجی میغزائے رنج
گراں بارئی درد عمرم بہ سنج
اگردیگراں را بود گفت و کرد
مرایا یہ عمر رنج است و درد
فرد ھل کہ حسرت خمیر من است
دم سردمن زمہریر من است
ایک بندہ مجبور کی زباں سے ایسی درخواست اورفرمائش کے لہجہ میں اور پھرکس سے۔ ایک ایسی ہستی سے جوساری کائنات کا آفریدگار اور پروردگار ہو، جو مختارکل ہو اور جس کا کام قیامت کے دن داوری کرنا اورانسان کے اعمال نیکی اوربدی کے اعتبار سے تولنا اور جزاوسزا کا حکم صادر کرناہے جتنی حیرت کی جائے کم ہے لیکن غالب کے لہجہ میں نہ خوف ہے نہ شرمندگی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غالب کویقین ہے کہ وہ جو کچھ عذرداری کررہے ہیں وہ برحق ہے اورجیسی زندگی ان کومیسر ہوئی تھی اس میں وہ وہی کرسکتے تھے جو وہ کرتے رہے لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوجاتی جب غالب کویہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ان کی شنوائی نہیں ہوگی اوران کے اعمال بھی پرسش اورپاداش سے بچ نہ سکیں گے تووہ نبردآمادگی کالہجہ اختیار کرتے ہوئے اس سے بھی زیادہ شوخی کی حد تک بڑھی ہوئی صاف گوئی سے کام لیتے ہیں۔
وگرہم چنین ست فرجام کار
کہ می باید از کردہ راندن شمار
مرا نیز یارائے گفتار دہ
چوگویم برآں گفتہ زنہار دہ
دریں خستگی پوزش از من مجو
بودبندہ خستہ گستاخ گو
دل از غصہ خوش شد نہفتن چہ سود
چوناگفتہ دانی نہ گفتن چہ سود
زبان گرچہ من دارم امازتست
بہ تست ارچہ گفتارم امازتست
ہماناتو دانی کہ کافر نیم
پرستار خرشید و آذر نیم
نہ کشتم کسے رابہ اھریمنی
نہ بردم زکس مایہ در رھزنی
مگر مے کہ آتش بہ گورم از دست
بہ ہنگامہ پرواز مورم از دست
من اندوھگین و مے اندہ ربائے
چی می کردم اے بندہ پرور خدائے
اور اگر بازپرس کرناہی ہے توپھر،
حساب مے و رامش ورنگ وبو
زجمشید وبہرام و پرویز جو
کہ از بادہ تا چہرہ افروختند
دل دشمن و چشم بد سوختند
مجھ سے کیا پوچھتے ہو جس نے کبھی خیرات سے کبھی قرض لے کرگاہ بگاہ دوگھونٹ پی کرمنہ کالا کرلیاہو۔
نہ از من کہ از تاب مے گاہ گاہ
بدریوزہ رخ کردہ باشم سیاہ
شبانگہ بہ مے رہ نمو نم شدے
سحرگہ طلب گار خونم شدے
تمنائے معشوقہ بادہ نوش
تقاضائے بیہودہ مے فروش
چہ گویم چوہنگام گفتن گذشت
زعمر گراں مایہ برمن گذشت
بساروزگاراں بہ دلدادگی
بسا نوبہاراں بہ بے بادگی
افقہا پر از ابر بہمن مہی
سفالینہ جام من از مے تہی
جہاں از گل ولالہ پر بوئے ورنگ
من و حجرہ و دامنے زیرسنگ
چہ خواہی زدلق مے آلود من
بہ بیں جسم خمیازہ فرسود من
اورپھر داورہی سے پوچھتے ہیں،
بہ فرمائے ایں داوری چوں بود
کہ از جرم من حسرت افزوں بود
اوریہ سب کچھ کہہ چکنے کے بعد اصرار کے ساتھ وہی طلب،
بہ بند امید استواری فرست
بہ غالب خط رست گاری فرست
یہ یادرہے کہ مثنوی کی ابتداحمد سے ہوئی ہے اور جس حصہ سے یہ اشعار لئے گئے ہیں اس کا عنوان ’’مناجات‘‘ ہے۔ درمیان میں ایک حکایت بھی آگئی ہے۔ اس کے بعد نعت ہے۔ معراج کا بیان ہے منقبت ہے اورمثنوی کا خاتمہ مغنی نامہ اور ساقی نامہ پرہوتاہے اوراتنی طویل ہونے کے باوجودمثنوی ناتمام رہ گئی ہے۔ اگر وہ مکمل ہوجاتی ہے تو نہ جانے کیاچیز ہوتی۔ جس طرح غالب نے آنکھیں برابر کرکے داور محشر سے گفتگو کی ہے وہ نہ صرف اس امرکی دلیل ہے کہ غالب کواپنے کردار اوراپنے اعمال پراعتماد ہے بلکہ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتاہے کہ غالب کو یقین ہے کہ داورمحشر بہرحال اپنا ہے اوراپنے بندوں کی بدانجامی گوارا نہیں کرے گا۔
اب سے کوئی ۴۵، ۴۶ سال پہلے کی بات ہے کارلائل (CARLYLE) کی شہرہ آفاق کتاب’’بطل اور بطل پرستی‘‘ (HERO AND HERO۔WORSHIP) میرے نصاب میں تفصیلی مطالعہ کے لئے داخل تھی۔ پڑھانے والا ایک تازہ وار اورخالص انگریزتھا جوآکسفورڈ سے انگریزی ادب میں فارغ التحصیل کی سند لے کر آیاتھا جب کتاب ختم ہوگئی تودوسری کتاب شروع کرنے سے پہلے اس نے جماعت کے لڑکوں سے یکے بعددیگرے سوال کیاکہ ’’بتاؤ اس کتاب کا مرکزی تصور کیاہے؟ جب کسی نے کوئی جواب نہیں دیاتو وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ میں نے کہا جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں۔ کتاب کا مرکزی تصور یہ ہے کہ ’’بطل یانابغہ ہرلقطہ پر اورہرحال میں بطل یانابغہ رہتا ہے۔‘‘
آج میں سوچتا ہوں تواکابر عالم میں گنتی کی چندہستیاں ایسی نکلیں گی جو میرے اس قول کی تصدیق میں پیش کی جاسکیں۔ انہیں چند ہستیوں میں غالب بھی ہیں اور کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ میں اس سے پہلے اشارہ کرچکا ہوں کہ غالب جس ملک میں بھی پیداہوتے اور جس زبان پربھی قدرت رکھتے وہ فکر وفن میں دنیاکی عظیم ترین شخصیتوں کے ہم پہلوہوتے اس کاثبوت ان کا اردواورفارسی کلام ہے۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ غالب شاعری کی کم وبیش ہرصنف میں اپنی امتیازی شان پیداکرلیتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ غزل قصیدہ اور مثنوی میں تو وہ یکساں عدیم المثل ہیں۔ تینوں اصناف میں اندازفکر اورطرزبیان دونوں کے اعتبار سے وہ مساوی قدرت کے مالک ہیں۔ اگران کی غزلیں سامنے نہ ہوں اور صرف ان کے قصیدوں کامطالعہ کیاجائے تووہ قصیدے کے شاعرہوتے ہیں اوران کی غزلوں اور قصیدوں کوبھول جایاجائے توان کومثنوی کا قادرالکلام شاعرماننا پڑے گا اور غزل کے شاعر تووہ ہیں ہی۔
غالب کی شخصیت اوران کی شاعری کی صحیح قدرمتعین کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان کے اردو دیوان کے ساتھ ان کے کلیات نظم فارسی کا بھی ذوق وتامل کے ساتھ مطالعہ کیاجائے لیکن اس برصغیر میں فارسی کے ساتھ دل بستگی دھیرے دھیرے کچھ اس طرح مٹی رہی ہے کہ عصرحاضر کے پڑھے لکھے لوگ فارسی ادب کے ذوق سے بالکل معراہوکر رہ گئے ہیں۔ غالب کے مشہور ترین ناقدین نے بھی ان کی فارسی شاعری یا نثری کارناموں کی طرف کوئی خاص اعتنانہیں کیا۔ ایسی صورت میں ڈاکٹرعارف شاہ گیلانی کی کتاب ’’شہنشاہ سخن‘‘ ایک نعمت معلوم ہوتی ہے جوغالب کے کلیات نظم و نثرپرایک محاکمہ ہے اور پرذوق تحقیق وتفحص کے بعدتیارکی گئی ہے۔ کاش یہ کتاب غالب کے ساتھ شغف رکھنے والوں کے لئے حوصلہ انگیز ثابت ہوسکے۔
غالب کا تصور ذہن میں آتے ہی مغرب کے بہت سے قدیم وجدید مشاہیرفکر وفن کی بھی یادآئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تقابلی تنقید میں بہت سے خطرے ہیں۔ تنقید غالب کے سلسلے میں اس طرز انتقاد میں ڈاکٹرعبدالرحمن بجنوری معلم اول کا درجہ رکھتے ہیں۔ مغرب ک کسی عہدکا شایدہی کوئی فلسفی شاعر ہوجس کوغالب کے مقابلہ میں نہ لایاگیا ہو۔ یہی نہیں یورپ کے عظیم سے عظیم نقاشوں سے بھی غالب کومشبہ دکھایاگیاہے۔ ڈاکٹربجنوری عالمی علوم وفنون سے قابل اعتبار واقفیت رکھتے تھے اورانہوں نے کہیں کوئی غیرمتعلق بات نہیں کہی ہے پھربھی ’’محاسن کلام غالب‘‘ پڑھتے وقت یہ احسا س ہوتا ہے کہ کہنے والا ایک خطرے کا شکار ہوہی گیا جس کواگرغلوکہا جائے تو نامناسب نہ ہوگا۔
لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں کسی ایک عظیم شخصیت کا ذکر کرتے ہوئے کسی مماثلت کی بناپرکسی دوسری شخصیت کانام لیاگیا تو سننے والا یا پڑھنے والا خود اپنے ذہن سے پیدا شدہ غلط فہمی میں مبتلا ہوجاتاہے اوریہ سمجھ لیتا ہے کہ جن دوشخصیتوں کے ساتھ نام لئے گئے ہیں وہ ہراعتبار سے مساوی اور ہم وزن ہوں گے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ مماثلت کے معنی عینیت یاہبوئیت نہیں ہوتے۔ میں خودجب غالب کے بارے میں سوچتا ہوں توشرق وغرب کے اکثرحکما عرفا شعرا وادباارباب ذوق ونظر اوراصحاب اسالیب وصور کی بے ساختہ یادآجاتی ہے۔ تخلیق یا کون وفساد کے تصور کا جہاں تک تعلق ہے غالب کے کلام میں افلاطون، ارسطو اورفلاطینوس سے ابن رشد اورمحی الدین ابن عربی تک اور محی الدین ابن عربی سے ہیگل، نطشے، بیرگساں اوردوسرے جدید حکماءکی جھلکیاں مل جاتی ہیں۔ فارسی کے جن شاعروں کی یاد غالب کے مطالعے کے دوران آتی رہتی ہے ان کے نام گنائے جاچکے ہیں۔ مغرب میں جرمنی کا آفاقی شہرت رکھنے والا حکیم شاعرگوئٹے اورانگلستان کے شاعروں میں ورڈسورتھ، شیلے اور براؤننگ غالب سے بہت کافی قرب رکھتے ہیں۔ غالب کا ظریفانہ طنز اور ان کی ’’دانشورانہ ظرافت‘‘ ہم کوکبھی سقراط اورکبھی یونان کے مشہور المیہ نگار سفوملیزکی یاد دلاتی ہے۔ اس کے یہ معنی توہرگز نہیں کہ غالب اوریہ گنائے ہوئے اساتذہ جملہ حیثیات میں مساوی الاضلاع اورمساوی الزوایا ہیں۔ یہ توصرف اس امرکی دلیل ہے کہ حقیقت کسی ایک ملک یاایک عہدیاچند مخصوص افراد کی میراث نہیں بلکہ ہرقوم اور عہد میں ایسے صاحب نظر اورصاحب دل پیدا ہوتے رہتے ہیں جوحقیقت کی جھلکیاں دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا کے اہل بینش اورارباب دانش ایک اخوت ہیں۔ یہ اخوت بددیت کے زمانہ سے تاحال اورکارفرما ہے اورہمیشہ زندہ اورکارفرما رہے گی۔ غالب بھی اس اخوت کے ایک عظیم اورموثر رکن ہیں۔
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.