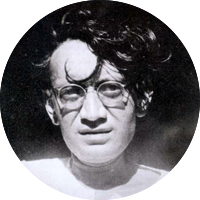میکسم گورکی
۱۸۸۰ء سے لے کر ۱۸۹۰ء کا درمیانی زمانہ جو خاص طور پر عقیم ہے، روس کی تاریخ ادب میں ایک نئے باب کا اضافہ کرتا ہے۔ دوستو وسکی ۱۸۸۱ء میں سپرد خاک ہوا، تو رگنیف ۱۸۸۳ء میں راہی ملک عدم ہوا اور تالستائی کچھ عرصہ کے لئے صناعانہ تصانیف سے روکش رہا۔ جب اس نے قلم اٹھایا تو ’’اینا کارنینا‘‘ اور ’’وار اینڈ پیس‘‘ کے مصنف نے بالکل جدا سپرٹ میں اپنے افکار کو پیش کیا۔ اسی دوران میں روسی معاشرت کی تبدیلیاں نمایاں طور پر ظاہر ہو گئیں۔ ۱۸۶۳ء میں مزارعوں کی آزادی کے بعد ملک کی صاحب اقتدار جماعت نے رفتہ رفتہ معاشی اقبال اور سیاسی اہمیت سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ بیشتر سرمایہ دار قریب قریب تباہ ہو چکے تھے اور ان کی جائیداد نوکسبیہ تاجروں کے ہاتھوں میں جا رہی تھی۔
الگزنڈر سوئم (۹۴۔ ۱۸۸۰ء) کا عہد حکومت اور نکولس دوئم (۱۹۱۷۔ ۱۸۹۴ء) کی حکمرانی کے پہلے چند سال روس کی اندرونی سیاسیات کا بدترین زمانہ ہے۔ جذبۂ اصلاح کا وہ جوش جو الگزنڈر دوئم کے عہد میں روسی معاشرہ کی رگوں میں موجزن تھا، اب سرد ہو چکا تھا۔ مہذب روسی، معاشرتی سوالات سے دور ہٹ کر صرف اپنے ذاتی معاملوں پر غور کرتے تھے۔ دوسری طرف انیسویں صدی کے آخری برسو ں میں مصنوعات نے بڑی ترقی کی اور بیشتر کسانوں نے کارخانوں کی مزدوری اختیار کر لی۔ یہ کسان اپنا گھر بار چھوڑ کر شہروں میں آباد ہو گئے، مگر پھر بھی ان کا اپنے دیہاتوں سے تعلق قائم رہا۔ جہاں وہ ٹیکس ادا کرتے تھے۔ ملک میں خانہ بدوش مزدوروں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ مزدوروں کی یہ جدید جماعت مارکس کے اشتراکی پروپیگنڈے کے لئے بہت موزوں تھی جو بعد میں روسی انقلاب کی محرک ہوئی۔ دو مصنف جو روس کے اس متبدل معاشرتی نظام کی تصویر کشی کرتے ہیں، چیخوف اور گورکی ہیں۔
چیخوف کی وفات سے قبل یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی تصانیف نے حقیقت نگاری کے سنہرے زمانے کا افتتاح کیا ہے۔ جس کا وہ انجام کار صرف پیش آہنگ تھا۔ ۱۸۹۵ء سے ۱۹۰۵ کے درمیانی عرصے میں بہت سے نوجوان ادیب یکے بعد دیگرے روسی فضا میں ابھرے۔ ان ادباء نے مقامی شہرت حاصل کرنے کے علاوہ اکناف عالم میں بھی اپنے نام کا ڈنکا بجوایا۔ دوستو وسکی اور تورگنیف سے بڑھ کر ان کو مقبولیت حاصل ہوئی، جن میں گورکی اور اینڈریف کے نام خاص مرتبہ اور حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم اس عصر کے ادیبوں کی اجتماعی ادبی سرگرمیوں کو گورکی اینڈریف اسکول کہیں گے۔ اس لئے کہ وہ تمام انشا پرداز جو اس اسکول میں شامل تھے، اپنے ہمراہ ایسی مشترکہ خصوصیات رکھتے ہیں، جو افسانہ نگاری کے قدیم ’’پری چیخوف‘‘ اسکول سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہیں۔
جس اسکول کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں گورکی کا نام خاص اہمیت رکھتا ہے اس لئے کہ ہمیں اس اسکول کے اکثر اراکین کی تحریروں پر اس کے افکار کا اثر نظر آتا ہے۔ اس اثر کی تمام تر وجہ یہ ہے کہ گورکی ہی پہلا شخص تھا جس نے روسی حقیقت نگاری سے ’’ملائم‘‘ اور ’’مطہر‘‘ عناصر یک قلم خارج کر دیے۔ روسی حقیقت نگاری اخلاقیات کے معاملہ میں ہمیشہ نرم و نازک رہی تھی۔ روسی ادیب، فرانسیسی ناولسٹوں کی خام کاری اور حد سے متجاوز صاف گوئی سے پرہیز کرتے تھے۔ (اس زمانے کا روسی ادب کسی حد تک انگریزی وکٹورین ناول سے مشابہت رکھتا ہے) بھدا پن، نجاست اور صنفی رشتوں کا شہوانی پہلو روسی مصنف کے لئےہمیشہ شجر ممنوعہ رہا تھا۔
یہ ’’ادبی معاہدہ‘‘ تالسٹائی نے منسوخ کیا۔ جس نے پہلی مرتبہ موت اور بیماری کی جسمانی ہیبتوں کو اپنا موضوع قرار دے کر ’’ایوان الیچ کی موت‘‘ نامی ایک تمثیل سپرد قلم کی اور محبت کے شہوانی پہلو کی ’’کرو تزر سوینٹا‘‘ کے اوراق میں نقاب کشائی کی۔ تالسٹائی نے ان دو کتابوں کے تعارف سے درحقیقت انیسویں صدی کے ممنوعات اور اعتقادات کی بنیادیں قطعی طور پر ہلا دیں۔ وہ کام جو تالسٹائی نے شروع کیا تھا، گورکی، اینڈریف اور آر ٹی بے شیف کے ہاتھوں تکمیل حاصل کرتا رہا۔ علاوہ بریں جدید آرٹ کا بانی ہونے کی حیثیت میں بھی تالسٹائی کا اثر کافی وافی تھا۔۔۔ افسانہ نگاری کے مافوق الطبعی مسئلے نے جو اس کے زیر نظر تھا، خاص طور پر اینڈریف اور آر ٹی بے شیف کے ہاتھوں خوب نشوونما حاصل کی۔
ادب پر چیخوف کا اثر جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ ایک حد تک مختصر افسانہ نگاری کو روس میں مروج و مقبول کرنے کا سہرا اسی کے سر ہے۔ بیشتر نوجوان افسانہ نگاروں نے چیخوف کا چربہ اتارنے یعنی اس کی صناعانہ باریک روی کو اپنانے کی کوشش کی، مگر اس فن میں اس کا کوئی مدمقابل نہ ٹھہر سکا، گو ہمیں ان نقال افسانہ نگاروں کی عبارت میں چیخوف کی دل پسند تراکیب اور اظہار خیال کی مخصوص طرز ملتی ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ اس کی صنعت بیانی کو وہ ہرگز نہیں پہنچ سکے۔
۱۹۰۰ء اور ۱۹۱۰ء کے درمیانی عرصہ میں روسی ادب دو مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اولاً۔ گورکی اینڈریف اسکول۔ ثانیاً اشارہ نگار اور ان کے پیرو۔ یہ لوگ ایسے جدید کلچر کے مبلغ تھے، جس نے روسی اذہان کی خوب تربیت کی اور طبقہ علمی کو بیک وقت یورپی اور قومی بنا دیا۔
روسی ادب کی حیات تازہ میں میکسم گورکی کا نام بلند ترین مرتبہ رکھتا ہے۔ جدید انشا پردازوں میں صرف گورکی ہی ایسا ادیب ہے جو تالسٹائی کی طرح اکنافِ عالم میں مشہور ہے۔ اس کی شہرت چیخوف کی مقبولیت نہیں جو دنیا کے چند ممالک کے علمی طبقوں تک محدود ہے۔
گورکی کا کردار فی الحقیقت بہت حیرت افزا ہے، غریب گھرانے میں پیدا ہو کر وہ صرف تیس سال کی عمر میں روسی ادب پر چھا گیا۔ طبقہ ادنیٰ کا شاعر بیسویں صدی کا بائرن میکسم گورکی زندگی کی تاریک ترین گہرائیوں کے بطن سے، جو جرائم مصائب اور بدیوں کا مسکن ہے، پیدا ہوتا ہے۔ اس نے فقیروں کی طرح ہاتھ پھیلا پھیلا کر روٹی کے سوکھے ٹکڑے کے لئےالتجا نہ کی اور نہ جوہری کی طرح اپنے بیش قیمت جواہرات کی نمائش سے لوگوں کی آنکھوں میں چکاچوند ہی پیدا کرنا چاہی۔ نزہنی نوو گوروکا یہ معمولی باشندہ اپنے حریت پسند افکار سے روسی ادب کی اندھی شمع کو تابانی بخشنے کا آرزو مند تھا۔ مردہ زرد اور بے جان ڈھانچوں میں حیاتِ نو کی تڑپ پیدا کرنا چاہتا تھا۔
میکسم گورکی کا اصلی نام الیکسی میکس مووخ پیشکوف ہے۔ اس کا باپ میکسم پیشکوف ایک معمولی دکاندار تھا جو بعد ازاں اپنی علو ہمتی اور محنت کشی سے استرا خان میں جہاز کا ایجنٹ بن گیا۔ اس نے نزہنی نوو گورو کے ایک رنگ ساز وسیلی کیشرن کی لڑکی سے شادی کی۔ جس کے بطن سے میکسم گورکی ۱۴ مارچ ۱۸۶۹ء کو پیدا ہوا۔ پیدائش کے فوراً بعد ہی باپ اپنے بچے کو استرا خاں لے گیا۔ یہاں گورکی نے ابھی اپنی زندگی کی پانچ بہاریں دیکھی تھیں کہ باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ اب گورکی کی ماں اسے پھر سے اس کے دادا کے گھر لے آئی۔
گورکی نے اپنے بچپن کے زمانے کی داستان اپنی ایک تصنیف میں بیان کی ہے۔ اس میں اس نے اپنے جابر دادا اور رحم دل دادی کے کرداروں کی نہایت فنکاری سے تصویر کشی کی ہے، جس کے نقوش قاری کے ذہن سے کبھی محو نہیں ہو سکتے۔ جوں جوں کم سن گورکی بڑا ہوتا گیا، اس کے گرد و پیش کا افلاس زدہ ماحول تاریک سے تاریک تر ہوتا گیا۔ اس کی ماں نے جیسا کہ گورکی لکھتا ہے، ’’ایک نیم عاقل شخص سے شادی کر لی۔‘‘ اس شخص کے متعلق گورکی کی کوئی اچھی رائے نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی والدہ بھی اسے داغ مفارقت دے گئی اور ساتھ ہی اس کے دادا نے اسے خود کمانے کے لئے اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔ قریباً دس سال تک نوجوان گورکی روس کی سرحدوں پر فکرِ معاش میں مارا مارا پھرتا رہا۔ کشمکش زیست کے اس زمانے میں اسے ذلیل سے ذلیل مشقت سے آشنا ہونا پڑا۔
لڑکپن میں اس نے ایک کفش دوز کی شاگردی اختیار کر لی۔ یہ چھوڑ کر وہ ایک مدت تک دریائے والگا کی ایک دخانی کشتی میں کھانا کھلانے پر نوکر رہا۔ جہاں ایک بوڑھے سپاہی نے اسے چند ابتدائی کتابیں پڑھائیں اور اس طرح اس کی ادبی زندگی کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان کتابوں میں سے جو گورکی نے تختہ جہاز پر بوڑھے سپاہی سے پڑھیں، ایک کتاب ’’اڈلفو کے اسرار‘‘ تھی، ایک مدت تک اس کے زیر مطالعہ ایسی کتب رہیں جن کے اوراق عموماً کشت و خون اور شجاعانہ رومانی داستانوں سے لبریز ہوا کرتے تھے، اس مطالعہ کا اثر اس کی اوائلی تحریروں میں نمایاں طور پر جھلکتا ہے۔
پندرہ برس کی عمر میں گورکی نے قازان کے ایک اسکول میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر جیسا کہ وہ خود کہتا ہے، ان دنوں مفت تعلیم دینے کا رواج نہیں تھا۔ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا بلکہ اسے بھوکوں مرنے سے بچاؤ حاصل کرنے کے لئے ایک بسکٹوں کے کارخانے میں کام کرنا پڑا۔ یہ وہی کارخانہ ہے جس کی تصویر اس نے اپنے شاہکار افسانے ’’چھبیس مزدور اور ایک دوشیزہ‘‘ میں نہایت فن کاری سے کھینچی ہے۔ قازان میں اسے ایسے طلبہ سے ملنے کا اتفاق ہوا، جنہوں نے اس کے دماغ میں انقلابی خیالات کی تخم ریزی کی۔ قازان کو خیرباد کہنے کے بعد وہ جنوب مشرق اور مشرقی روس کے میدانوں میں آوارہ پھرتا رہا۔ اس زمانہ میں اس نے ہر نوعیت کی مشقت سے اپنا پیٹ پالا۔ اکثر اوقات اسے کئی کئی روز فاقے بھی کھینچنے پڑے۔
۱۸۹۰ء میں وہ نزہنی میں رنگروٹ بھرتی ہونے کے لئے آیا۔ خرابی صحت کی بنا پر اسے یہ ملازمت تو نہ مل سکی مگر وہ نزہنی کے ایک وکیل مسٹر ایم اے لینن (1)1 کے یہاں منشی کی حیثیت میں نوکر ہو گیا۔ اس وکیل نے اس کی تعلیم کی طرف بہت توجہ دی۔ تھوڑے عرصہ کے بعد ہی گورکی کے ذہنی تلاطم نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ منشی گیری چھوڑ کر روس کی سرحدوں پر آوارہ پھرے۔۔۔ دراصل قدرت کو یہ منظور نہ تھا کہ مستقبل قریب کا ادیب اتنے عرصے تک دنیا کی نظروں سے روپوش رہے۔ خانہ بدوشی کی اس سیاحت کے زمانے میں گورکی (2)2 نے اپنا قلم اٹھایا۔ ۱۸۹۲ء میں جب کہ وہ تفلس کے ایک ریلوے ورکشاپ میں ملازم تھا، اس کا پہلا افسانہ ’’ماکارشدرا‘‘ جو ایک نہایت دلچسپ رومانی داستان تھی، مقامی روزنامہ ’’قفقاز‘‘ میں شائع ہوا۔ اس افسانے میں اس نے خود کو اپنے قلمی نام گورکی سے متعارف کرایا۔ یہ نام اب ہر فرد بشر کی زبان پر ہے۔
کچھ عرصہ تک وہ اپنے صوبے کے اخباروں میں مضامین چھپوانے کے بعد اس قابل ہو گیا کہ اپنی تحریروں سے روپیہ پیدا کر سکے۔ مگر ’’اعلیٰ ادب‘‘ کے ایوان میں وہ اس وقت داخل ہوا، جب اس نے دوبارہ نزہنی میں اقامت اختیار کی۔ کور لنکو (3)3 ، ان دنوں نزہنی میں تھا۔ اس نے گورکی کا ایک افسانہ ’’چلکاش‘‘ اپنے اثر و رسوخ سے اس وقت کے ایک مؤقر مجلہ میں شائع کرایا۔ گومیکسم گورکی نے پراونشل پریس کی قلمی اعانت جاری رکھی۔ مگر پیٹرز برگ کے رسائل بھی اس کے مضامین شکریہ کے ساتھ شائع کرنے لگے۔۔۔ ۱۸۹۵ء میں اس کے افسانوں کا پہلا مجموعہ کتابی صورت میں شائع ہوا۔ ان افسانوں کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ فی الحقیقت روسی انشا پرداز کے لئے اس قسم کی شاندار کامیابی غیر مسبوق تھی۔ اس کتاب کے تعارف کے ساتھ ہی گورکی ایک غیر معروف جرنلسٹ سے ملک کا مشہور ترین انشا پرداز بن گیا۔
گورکی کی شہرت ’’پہلے انقلاب‘‘ تک قابل رشک تھی۔ ملک کے تمام اخبار اس کی تصاویر اور اس کے ذکر سے بھرے ہوتے تھے۔ ہر شخص اس کے سراپا کو ایک نظر دیکھنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ بین الملی شہرت بھی فوراً ہی نوجوان مصنف کی قدم بوسی کرنے لگی۔ جرمنی بالخصوص اس پر لٹو ہو گیا۔۔۔ ۱۹۰۳ء اور ۱۹۰۶ء کے درمیانی عرصہ میں گورکی کی شاہکار تمثیل ’’تاریک گہرائیاں‘‘ برلن کے ایک تھیٹر میں متواتر پانچ سو راتوں تک سٹیج ہوتی رہی۔ پیٹرز برگ میں گورکی کا بیشتر وقت مارکسیوں کی صحبت میں گزرا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مارکسی بن گیا اور اس نے اپنی دو تصانیف ’’وہ تینوں‘‘ اور ’’فوما‘‘ ایک مارکسی مجلہ کے سپرد کر دیں۔ یہ دونوں کتابیں اس رسالے میں بالاقساط شائع ہوئیں۔ گورکی کے ایک گیت کی اشاعت کی وجہ سے یہ رسالہ حکومت نے ضبط کر لیا۔ یہ گیت آنے والے انقلاب کی ایک بے نقاب تمثیل تھی۔
میکسم گورکی اب روس کی جمہوریت پسند دنیا کی سب سے زیادہ اہم اور مشہور شخصیت تھی۔ مالی نقطۂ نظر سے بھی اسے بہت اہمیت حاصل تھی۔ اس کی تصانیف کا پیدا کردہ روپے کا بیشتر حصہ انقلاب کی تحریک میں صرف ہوتا رہا۔ خرچ کا یہ سلسلہ ۱۹۱۷ء کے اختتام تک جاری رہا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ گورکی اپنی کتابوں کی مقبولیت اور حیرت افزا فروخت کے باوجود اپنی محنت کے ثمر سے پوری طرح حظ نہ اٹھا سکا۔ ۱۹۰۰ء میں روس کی فضا سخت مضطرب تھی۔ گرفتاریوں اور سزاؤں کی بھرمار تھی، چنانچہ گورکی گرفتار ہوا اور اسے پیٹرز برگ سے نکال کر نزہنی میں نظربند کر دیا گیا۔ ۱۹۰۲ء میں اسے ’’امپیریل اکیڈمی آف سائنس‘‘ کا اعزازی رکن منتخب کیا گیا، مگر چونکہ نئی اکادمی پولیس کی زیرنگیں تھی اس لئے حکومت نے فوراً ہی اس انتخاب کو رد کر دیا۔ اس پر کور لنکو اور چیخوف سخت مشتعل ہوئے اور احتجاج کے طور پر ادکامی سے علیحدہ ہو گئے۔
پہلے انقلاب میں گورکی نے بڑی سرگرمی سے حصہ لیا۔ جنوری ۱۹۰۵ء میں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس گرفتاری نے اکناف عالم میں گورکی کے چاہنے والے پیدا کر دیے۔ رہائی کے بعد گورکی نے ایک روزانہ اخبار شائع کیا جس کے کالم بالشویک تحریک کے نشوو ارتقاء کے لئے مخصوص تھے۔ اس روزنامے میں گورکی نے بیسویں صدی کے تمام روسی ادباء کو بیہودہ قرار دیتے ہوئے مقالوں کا ایک تانتا باندھ دیا۔ ان انشاء پردازوں میں جو اس کے نزدیک فضول تھے، تالسٹائی اور دوستو وسکی بھی شامل تھے، وہ انہیں ادنیٰ سرمایہ دار کا نام دیتا ہے۔
اس زمانے میں روس کے غیر ملکی قرضوں کی بہت مخالفت ہو رہی تھی۔ گورکی نے اس تحریک میں بڑی گرم جوشی سے حصہ لیا اور دسمبر میں ماسکو کی ’’مسلح بغاوت‘‘ کی ہر ممکن طریق پر مدد کی۔ ۱۹۰۶ء میں روس چھوڑ کر وہ امریکہ چلا گیا۔ اس کا فن لینڈ اور سیکنڈے نیویا کا سفر ایک پرشکوہ اور ظفر مند جلوس کی صورت میں تھا۔ امریکہ میں اس کا استقبال نہایت شاندار طریقے پر کیا گیا، مگر فوراً ہی وہاں کے لوگوں کو پتا چل گیا کہ گورکی جس عورت کے ہمراہ رہتا ہے اور جسے اپنی منکوحہ بیوی بتاتا ہے، فی الحقیقت اس کی بیوی نہیں۔ اس واقعہ نے امریکیوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا کر دی۔ اسے ہوٹل چھوڑ دینے کے لئے کہا گیا اور ایک دعوت میں جو اس کے اعزاز میں دی جا رہی تھی، ما رک ٹوین (4)4 نے صدارت سے انکار کر دیا۔ قدرتی طور پر گورکی ’’طہارت‘‘ کے اس غیر متوقع جذبے سے سخت رنجیدہ ہوا۔ جو ایک روسی کے لئے ناقابل فہم تھا۔ اس ذہنی تکدر نے اسے چند امریکی افسانے سپرد قلم کرنے پر مجبور کیا۔ جو ۱۹۰۷ء میں ’’پیلے بھوتوں کا شہر‘‘ کے معنی خیز عنوان سے شائع ہوتے رہے۔
یورپ واپس آنے پر وہ ’’کیپری‘‘ میں سکونت پذیر ہوا۔ جہاں وہ ’’جنگ‘‘ سے کچھ عرصہ پہلے تک مقیم رہا۔ یہاں کے لوگوں میں اسے بہت ہر دلعزیزی نصیب ہوئی۔ میسینا کی ہولناک آفت کے بعد ریلیف کے کاموں میں حصہ لینے کی وجہ سے اٹلی، گورکی کا گرویدہ ہو گیا۔ اسی عرصہ میں روس کے ادبی حلقوں میں اس کی شہرت کم ہونے لگی۔ ’’تاریک گہرائیاں‘‘ کے بعد کی تصانیف کو وہ مقبولیت حاصل نہ ہوئی جو ہونا چاہیئے تھی (رفتہ رفتہ گورکی جو ۱۹۰۰ء تک بڑا ہر دل عزیز مصنف تھا، بالشویک پارٹی کا پٹھو بن کر رہ گیا۔) پرنس، ڈی ایس میر سکی کونٹپریری رشین لٹریچر) گو ادبی حلقوں میں اس کی شہرت کو اس طرح زوال پہنچا، مگر دوسری طرف اس کے افکار روسی مزدوروں کے دل و دماغ میں گھر کرنے لگے۔ روسی مزدوروں کی وہ ذہنیت جو ہمیں ۱۹۱۷ء تک نظر آتی ہے۔ در اصل گورکی کی تصانیف کی مرہون منت ہے۔ روس واپس آنے پر اس نے ایک ماہانہ رسالہ جاری کیا، مگر یہ مقبول نہ ہوا۔
جنگ عظیم چھڑنے پر گورکی نے بین الملی پوزیشن اختیار کر لی۔ ۱۹۱۷ء میں اس نے اپنے قدیم دوستوں یعنی بالشویکوں کی مدد کی، مگر یہ امداد غیر مشروط نہ تھی۔ گو اس کا اثر لینن اور اس کی پالیسی کے حق میں تھا مگر اس نے اس دفعہ خود کو پارٹی کا طرف دار ظاہر نہ کیا۔ بلکہ غیر جانبدار اور امن پسند رہنے کی کوشش کی، اس کی یہ بھاری بھر کم برتری اور مشفق مگر حرف گیر علیحدگی دیر تک قائم رہی۔ بالشویکوں نے اس رویے پر ضرورت سے زیادہ سرگرمی کا اظہار نہ کیا، لیکن ایک طرف گورکی کے بالشویک پارٹی کے سرکردہ لیڈروں سے ذاتی تعلقات، دوسری طرف اس کی بیرونی شہرت کی فروانی نے اسے ایک اعلیٰ حیثیت بخشی۔۔۔ ۱۹۱۸ء سے لے کر ۱۹۲۱ء تک قطعی طور پر سوویٹ روس میں پبلک کی آزاد قوت صرف گورکی ہی تھی۔
گورکی کے غیر جانبدارانہ رویہ کو قابل تحسین قرار نہ دیا جائے، مگر یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس ہولناک زمانہ میں اس کی سرگرمیاں قابل صد آفرین ہیں، اگر وہ اس سے قبل امن پسند اور تہذیب و تمدن کا حامی بننے کا جھوٹا دعوی کر رہا تھا تو اس نے اس مرتبہ فی الواقع اپنے آپ کو ایسا ثابت کر دکھایا۔ روسی تمدن درحقیقت گورکی کی اخلاص کیشانہ سرگرمیوں کا شرمندہ احسان ہے۔ ۱۹۱۸ء اور ۱۹۲۱ء کے دوران میں ہر وہ کوشش جو روسی انشا پردازوں اور دیگر صحافیوں کو گرسنگی سے بچانے کے لئے عمل میں لائی گئی، صرف گورکی کی توجہ کا نتیجہ تھی۔ اس نے اس غرض کے لئے اپنے سیاسی دوستوں کی مدد سے ایک ایسا مرکزی ادارہ قائم کیا، جہاں روسی ادباء سے غیر ملکی زبانوں کے تراجم کرائے جاتے تھے اور اس طرح انہیں پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہو جاتا تھا۔
۱۹۱۹ء میں گورکی نے ’’تالسٹائی کی یاد کی جھلکیاں‘‘ شائع کی۔ اس تصنیف سے ایک بار پھر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ فی الواقع اعلیٰ پائے کا مصنف ہے مگر اس کے باوجود وہ اپنی پہلی سی عظمت دوبارہ حاصل نہ کر سکا۔ ۱۹۲۲ء میں اس نے روسی کسانوں پر ایک زبردست مقالہ لکھا جس میں اس نے اس جماعت کو غیر معمولی ترش الفاظ میں ملامت کرتے ہوئے اسے ہر برائی کا مسکن قرار دیا ہے۔ گورکی اس جماعت کے افراد کو اس لئے بھی مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ انہوں نے قومی تہذیب کی تاسیس میں کوئی حصہ نہ لیا۔ ۱۹۲۲ء کے آخر میں گورکی نے روس کو خیرباد کہہ کر جرمنی میں سکونت اختیار کر لی۔ اس کی صحت جو پہلے ہی بہت خراب تھی اور زیادہ خراب ہو گئی لیکن اس کے باوجود اس نے قلم اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ وہ ایک رسالے کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیتا رہا۔ جس کے ذریعے وہ سائنس کی جدید ترقی کو اپنے ملک سے روشناس کرانا چاہتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے گورکی کے پیش نظر صرف یہی چیز ہے اس لئے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ابتدائی علم کی نشر و اشاعت ہی ملک کی سب سے اہم ضرورت ہے۔
اخباری اور محض سیاسی تحریروں کو شامل نہ کرتے ہوئے ہم گورکی کی باقی تصانیف تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں،
۱۔ وہ مختصر افسانے جو ۱۸۹۲ء اور ۱۸۹۹ء کے درمیانی عرصہ میں سپرد قلم ہوئے اور جن کی وجہ سے اسے مقبولیت حاصل ہوئی۔
۲۔ اس کے معاشرتی ناول اور ڈرامے جو ۱۸۹۹ء اور ۱۹۱۲ء کی درمیانی مدت میں لکھے گئے ہیں۔
۳۔ ۱۹۱۳ء سے لے کر اس وقت تک کی تمام تحریریں جو زیادہ تر سوانح حیات اور تذکروں کی شکل میں ہیں۔
گورکی کی تصانیف کا پہلا اور آخری دور، درمیانی زمانے کی تحریروں کی نسبت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ان تحریروں میں ہم اس کی تخلیقی قوت ایک حد تک ضعیف دیکھتے ہیں۔ گورکی کی اوائلی تصانیف کی حقیقت نگاری میں رومانیت بدرجہ اتم موجو د ہے۔ رومانیت کا یہی عنصر روس میں اس کی مقبولیت کا باعث ہوا لیکن اس کے برعکس غیر ممالک میں اس کی شہرت کا باعث اس کی حقیقت نگاری ہے۔ اس کے پہلے افسانوں کی تازگی روسی قاری کی نظر میں صرف اس کے جوان اور بے باک افکار تھے، لیکن غیر ملکی قاری اس خام اور ستم کار انداز بیان میں تازگی محسوس کرتا تھا جس کے ذریعے اس نے اپنی دوزخ نما دنیا کی تصویر کشی کی ہے۔ (کونٹمپریری رشین ناولسٹس، سرگ پر سکی)
ان سطور سے ہمیں ’’اوائلی گورکی‘‘ کے متعلق روسی اور غیر روسی قاری کی پسندیدگی کے تقابل کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اس تضاد کی وجہ فی الحقیقت ’’عقبی مناظر‘‘ کا تخالف ہے۔ روسیوں نے اس کے افکار کو چیخوف اور ۱۸۸۰ء کے دیگر انشا پردازوں کے گرائے ہوئے مغموم اور یاس آفرین پردے پر دیکھا اور غیر ملکیوں نے عہد وکٹوریہ کی مروّج و پرسکون حقیقت نگاری کے پردے پر۔ گورکی کے شروع شروع کے افسانے بالکل رومانیت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان افسانوں میں ’’ماکارشدرا‘‘ اور ازر گل۔۔۔ بڈھا آدمی‘‘ کے نام قابل ذکر ہیں۔
ان افسانوں کی رومانیت نمائشی اور تھیٹری ہے، لیکن اسی رومانیت نے چیخوف سے اچاٹ روسی قاری کی نظر میں گورکی کا رتبہ پیدا کیا۔ اس کی یہ رومانیت ایک ایسے فلسفے کی شکل اختیار کر گئی، جسے اس نے بڑے خام اور سادہ انداز میں اپنی ایک کہانی میں بیان کیا ہے۔ اس کہانی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دروغ جو روح کو سرفرازی بخشے، بہتر ہے اس سچائی سے جو ذلت آفرین ہو۔ ۱۸۹۵ء میں گورکی نے دفعتاً چوروں اور جنگلی انسانوں کی داستانیں قلم بند کرنا چھوڑ کر نیا رخ بدلا۔ اب اس نے جو روش اختیار کی، وہ حقیقت نگاری کی تشکیل اور رومانیت کا اجتماع تھا۔ اس کا پہلا افسانہ ’’چلکاش‘‘ جو بڑے پریس میں شائع ہوا، بہت کامیاب ہے۔ اس داستان کا موضوع چلکاش نامی ایک ترش رو اور نڈر خفیہ فروش اور اس نوجوان طامع لڑکے کا تقابل ہے جسے چلکاش اپنے خطرناک اور مجرمانہ پیشے کا شریک بناتا ہے۔ اس کہانی کا پلاٹ نہایت سلجھا ہوا اور دلچسپ ہے۔ چلکاش کا کردار قابل تعریف صفائی اور بہترین فن کاری سے پیش کیا گیا ہے۔ اسی قسم کے دو اور افسانے ’’مالوا‘‘ اور ’’میرا ہم سفر‘‘ ہیں۔
اوّل الذکر افسانے میں مالوا عورت کے بھیس میں دوسرا چلکاش ہے۔ مؤخر الذکر داستان کردار نگاری کے نقطہ نظر سے غیر فانی حیثیت رکھتی ہے۔ ’’میرا ہم سفر‘‘ میں پرنس شاد کو (جس کے ہمراہ داستان گواڈویسا سے ٹفلس تک پیدل سفر کرتا ہے) کا کردار فی الحقیقت گورکی کی نادر تخلیق ہے۔ شارکو کے کردار میں مثالیت کاشمہ بھر موجود نہیں۔ گویہ صاف ظاہر ہے کہ مصنف کی صناعانہ ہمدردی صرف اسی کے حق میں ہے۔
ان خصوصیتوں میں سے جو گورکی کی شہرت کا باعث ہوئیں، ایک اس کے نیچر (5)5 کو بیان کرنے کا خاص انداز ہے۔ ہم یہاں مثال کے طور پر اس کے افسانوں میں سے چند جملے پیش کرتے ہیں، ’’لنگرگاہ کے گردوغبار میں جنوبی آسمان گدلا نظر آتا ہے۔ تاباں سورج سنہری مائل سمندر کو دھندلی نگاہوں سے دیکھتا ہے، جیسے اس نے خاکستری نقاب اوڑھ رکھی ہے۔ سورج کا عکس سمندر کی سطح پر چپوؤں کے تھپیڑوں، دخانی کشتیوں اور ترکی جہازوں کی نقل و حرکت کی وجہ سے نہیں پڑ رہا، جو بندرگاہ پر ہل چلا رہے ہیں یہاں سمندر کی آزاد لہریں سنگین دیواروں میں قید اور ان بھاری وزنوں کے نیچے دبی ہوئی، جو ان کے سینے کو کچلتے ہیں، جھاگ بن کر اپنی چھاتی کوٹتی ہیں اور شکایت کرتی ہیں۔‘‘ (از چلکاش)
’’ہم نے الاؤ روشن کیا اور اس کے قریب لیٹ گئے۔ رات بہت شاندار تھی۔ گہرے سبز سمندر کی لہریں نیچے چٹانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ ہمارے اوپر نیلگوں آسمان کی پرشکوہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہمارے گردوپیش عطر بیز درخت تھے۔ جھاڑیاں بڑی آہستگی سے جھوم رہی تھیں۔ چاند بلند ہو رہا تھا۔ جس کے ساتھ درختوں کے نازک سایوں کا جھرمٹ پتھروں پر رینگ رہا تھا۔ قریب ہی کوئی خوش گلو پرندہ راگ الاپنے میں مصروف تھا۔ اس کی نقرئی آواز فضا میں، جو لہروں کے تھپیڑوں کی دھیمی اور دل نواز صدا سے معمور تھی، آہستہ آہستہ حل ہوتی معلوم ہوتی تھی۔۔۔ آگ تیزی سے جلنے لگی۔ الاؤ سے شعلے سرخ اور زرد پھولوں کا ایک گلدستہ نظر آتے تھے۔ کانپتے ہوئے سائے ہمارے آس پاس رقص کر رہے تھے۔‘‘ (از میر اہم سفر)
’’موسم بہار کے سورج کی کرنیں بادلوں سے چھن چھن کر پانی کی سطح پر زرنگاری کا کام کر رہی تھیں۔ ہوا کا جھونکا آنے پر نیچر انتہائی مسرت میں مسکرا دی۔ بادلوں میں چھپا ہوا نیلگوں آسمان بھی مسکرا رہا تھا۔ بادلوں کا گروہ جو فضا میں غیر متحرک لٹک رہا تھا، چمکیلے پانی کے اوپر کسی گہری سوچ میں غرق تھا گویا وہ آتش سورج سے بچنے کے لئے کوئی راستہ تلاش کر رہا تھا۔ اس شوخ رنگ اور پر از مسرت سورج سے جو طوفان کے ان نشانوں کا دشمن ہے۔‘‘ (از کلک پر)
گورکی کے بیشتر افسانوں میں اس قسم کی تفصیلات عام ہیں۔ اس کی تحریروں میں لہریں اور نیلگوں آسمان کی پراسرار اور پرشکوہ خاموشی کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ ’’مالوا‘‘ کا افتتاحیہ جملہ جو صرف دو لفظوں یعنی ’’سمندر ہنس رہا تھا‘‘ پر مشتمل ہے، اس کے طرز بیان کی مخصوص مثال ہے۔
۱۸۹۷ء میں گورکی کی حقیقت نگاری اس کی رومانیت پر غالب آ گئی۔ ’’جو کبھی انسان تھے‘‘ اس پر شاہد ہے۔ ’’اس افسانے اور ہر اس افسانے میں جو گورکی نے ۱۸۹۷ء کے بعد قلم بند کیا، ایک ایسی خصوصیت نمایاں طور پر ظاہر ہے جو اس کی ادبی شہرت کے زوال کا باعث ہے۔ یہ خصوصیت ’’فلسفیانہ گفتگوؤں‘‘ سے حد سے زیادہ بڑھا ہوا پیار ہے۔ جب تک اس نے اس عنصر سے پرہیز کیا، وہ اپنی تعمیری قوت کا ثبوت دیتا رہا، جو دیگر افسانہ نگاروں میں بہت کم ملتی ہے۔ گورکی کا وہ افسانہ جو اس کے ان تمام ادبی عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ’’چھبیس مزدور اور ایک دوشیزہ ہے‘‘ جو اس نے ۱۸۹۹ء میں لکھا۔‘‘ (پرنس ڈی ایس میرسکی)
اس افسانے کا افتتاحی منظر بسکٹ بنانے کا ایک تنگ و تار کارخانہ ہے، جہاں چھبیس مزدور روزانہ چودہ گھنٹے لگاتار مشقت کرتے ہیں۔ گورکی اس افسانے کو اپنے مخصوص انداز میں اس طرح شروع کرتا ہے، ’’ہم تعداد میں چھبیس تھے۔ چھبیس متحرک مشینیں۔ ایک مرطوب کوٹھری میں مقید۔ جہاں ہم صبح سے لے کر شام تک بسکٹوں کے لئے میدہ تیار کرتے۔ ہماری زنداں نما کوٹھری کی کھڑکیاں، جن کا نصف حصہ آہنی چادر سے ڈھکا تھا اور شیشے گردوغبار سے اٹے ہوئے تھے، اینٹوں اور کوڑے کرکٹ سے بھری ہوئی کھائی کی طرف کھلتی تھی۔ اس لئے سورج کی شعاعیں ہم تک نہ پہنچ سکتی تھیں۔
ہمارے آقا نے کھڑکیوں کا نصف حصہ اس لئے بند کرا دیا تھا کہ ہمارے ہاتھ اس کی روٹی سے ایک لقمہ بھی غریبوں کے دینے کے لئے باہر نہ نکل سکیں یا ہم ان بھائیوں کی مدد نہ کر سکیں جو کام کی قلت کی وجہ سے فاقہ کشی کر رہے تھے۔ اس سنگین زندان کی چھت تلے جو دھوئیں کی سیاہی اور لکڑی کے جالے سے اٹی ہوئی تھی، ہم نہایت تکلیف دہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس چاردیواری میں جو کیچڑ اور میدے کے خمیر سے بھری ہوئی تھی، ہماری زندگی غم و فکر کی زندگی تھی۔‘‘
اس افسانے کے متعلق کچھ اور لکھنے سے پیشتر ہم گورکی کے پیش کردہ کرداروں پر مختصر تبصرہ کرنا چاہتے ہیں۔ ’’ گورکی کی اپنی بیشتر تصانیف میں مزدوروں اور غربت زدہ کسانوں کو انسان (6)6 کی صورت میں پیش نہیں کرتا۔‘‘ یہ چیز یورپی ذہن کے لئےجو خوشگوار ماحول کا عادی ہے، نئی اور عجیب حیثیت رکھتی ہو تو کوئی اچنبھا نہیں ہے، مگر ہندوستان اور روس کے اس زمانے کی فضا سے صدگونہ مماثلت رکھتا ہے، ان کرداروں کو جو کبھی انسان تھے بخوبی سمجھتا ہے۔
جب گورکی ’’چھبیس متحرک مشینیں‘‘ لکھتا ہے تو ہمیں تعجب نہیں ہوتا۔ ہم فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ یہ لفظ ناکامی، حزن و ملال اور تاریک زندگی کا مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ گورکی انسان کو اس شکل میں پیش نظر رکھتا ہے جیساکہ وہ ہے۔ اس کے کردار بھوک کو ’’معاشی دباؤ‘‘ نہیں کہتے۔ وہ اسے صرف بھوک کہتے ہیں۔ وہ امراء کو ’’سرمایہ دارانہ عناصر کا اجتماع‘‘ نہیں کہیں گے۔ وہ انہیں صرف ’’امراء‘‘ کا نام دیں گے۔
گورکی کی یہ سادہ بیانی اور صاف گوئی اس کی تمام تصانیف میں موجود ہے۔ ’’چھبیس متحرک مشینیں‘‘ لکھتے وقت غالباً گورکی کے پیش نظر یہ تھا کہ وہ نہایت سادہ اور مختصر الفاظ میں ان مظلوم مزدوروں کی صحیح تصویر ناظر کے سامنے پیش کرے اور یہ حقیقت ہے کہ ’’چھبیس متحرک مشینیں‘‘ پڑھتے وقت ان مزدوروں کی لامتناہی محنت و مشقت اور بے بسی کی ایک صا ف تصویر کھنچ جاتی ہے۔
اس افسانے میں چھبیس زشت رو غلیظ مزدوروں کی ایک داستان بیان کی گئی ہے۔ یہ سب ایک حسین لڑکی ٹینیا کی محبت میں گرفتار ہیں، جو ہر روز ان سے بسکٹ لینے کے لئے آتی ہے۔ اس لڑکی کا معصوم حسن ہی ایک ایسی شعاع ہے، جس سے ان کی تاریک زندگی آشنا ہے۔ ان لوگوں کو جو سب کے سب غلیظ اور ان میں سے اکثر مریض ہیں، صرف ایک چیز منسلک کئے ہوتی ہے۔ یعنی ٹینیا سے ان کی جذباتی محبت، گورکی بڑے صاف انداز میں ان کی اس اجتماعی محبت کی تشریح کرتا ہے۔
’’ہم صنف نازک کے متعلق ایسے الفاظ میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات ہماری گفتگو ناگوار ہو جایا کرتی تھی۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ نہ کیا جائے کہ ہمارے خیالات عورتوں کے متعلق بہت برے تھے بلکہ وہ صنف جس کے متعلق ہم اظہار خیالات کرتے تھے، عورت کہلانے کی مستحق ہی نہیں، مگر ٹینیا کی شان میں ہمارے منہ سے کبھی گستاخ کلمہ نکلنے نہ پاتا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ ہمارے پاس بہت کم ٹھہرتی تھی۔ وہ آسمان سے ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح روشنی دکھلا کر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جایا کرتی تھی یا اس کی وجہ اس کا حسن ہو۔ کیونکہ ہر حسین چیز انسان کے دل میں اپنی وقعت پیدا کر دیتی ہے۔ خواہ انسان غیر تربیت یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔
اس کے علاوہ ایک اور بھی وجہ تھی۔ گو زندان نے ہم سب کو وحشی درندوں سے بدتر بنا دیا تھا مگر ہم پھر بھی انسان تھے اور بنی نوع انسان کی طرح ہم بھی کسی کی پرستش کئے بغیر زندہ نہ رہ سکتے تھے۔ ہمارے لئے اس کی ذات سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی شے نہ تھی۔ اس لئے کہ بیسیوں انسانوں میں جو اس عمارت میں رہتے، ایک صرف وہی تھی جو ہماری پرواہ کیا کرتی تھی۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی۔ ہر روز اس کے لئے بسکٹ مہیا کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے تھے۔ یہ ایک نذرانہ ہوتا جو ہم ہر روز اپنے دیوتا کی قربان گاہ پر چڑھاتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ رسم ایک مقدس فرض ہو گئی۔ جس کے ساتھ ہمارا اور اس کا رشتہ بھی باہم مضبوط ہو گیا۔ ہم ٹینیا کو نصیحتیں بھی کیا کرتے۔ یہی کہ وہ سردی میں گرم کپڑے استعمال کیا کرے اور سیڑھیوں پر سے احتیاط کے ساتھ گزرا کرے۔
مندرجہ بالا سطور سے مزدوروں کے کردار کا بچپن نمایاں طور پر ظاہر ہے۔ اس بچپن سے گورکی کو یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ چھبیس غیر تربیت یافتہ مزدور کس غیر معمولی اخلاص اور سادگی سے ٹینیا کی محبت میں گرفتار تھے۔ در اصل ان مزدوروں کو اپنی تاریک زندگی میں صرف ایک ہی شعاع نظر آئی جس کا دامن انہوں نے پکڑ لیا۔ گو یہ لوگ غلیظ، وحشی، جاہل اور غیر تربیت یافتہ ہیں، لیکن بایں ہمہ ان کے کھردرے قلوب پر ٹینیا کا وجود پورا اثر کرتا ہے، جسے وہ حقیقی حسن تصور کرتے ہیں۔ یہ لوگ خود اپنی غربت اور پر از مصائب زندگی کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، مگر یہ ان کا قصور نہیں کہ وہ مذہب اور آئیڈیل نہیں رکھتے۔ وہ امید اور خواہش زندگی سے ناآشنا ہیں۔
روسی مجلسی دائرے میں آراء و افکار کی نااستواری کا وجود، جیسا کہ گورکی خود کہتا ہے، ’’مثالیت سے غفلت برتنے کا نتیجہ ہے۔‘‘ ٹینیا چھبیس مزدوروں کی نظر میں ایک فرشتہ ہے۔ اس کی عصمت، پاکیزگی اور نیکی نہ صرف ان کی گفتگوؤں کا موضوع ہوتی ہے، بلکہ وہ ان مزدوروں کی زندگی کو نئے معانی بخشتی ہے۔ بڑے ڈرامائی اور بے رحم انداز میں گورکی اپنے پیش نظر مقصد کو رفتہ رفتہ ظاہر کرتا ہے۔ چھبیس پجاری اپنی دیوی کی عصمت کا امتحان لیتے ہیں۔ ایک سپاہی جو اس کارخانے میں ان کی بہ نسبت اچھے کام پر نوکر ہے، ان سے دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ ٹینیا کو ہتھے چڑھا لے گا۔ مزدور سپاہی سے شرط تو لگا بیٹھتے ہیں، مگر وہ ایک بے قراری مول لے لیتے ہیں۔
’’اب ہمیں معلوم ہوا کہ ہم شیطان سے بازی لگا رہے ہیں۔ جب ہم نے کیک بنانے والے سے سنا کہ سپاہی نے ٹینیا کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے تو ہمیں سخت رنج پہنچا۔ ہم اس رنج کو مٹانے کے لئے اس قدر محو تھے کہ ہمیں یہ معلوم تک نہ ہوا کہ آقا نے ہماری بے چینی اور اضطراب سے فائدہ اٹھا کر میدے میں تیس سیر کا اضافہ کر دیا ہے۔‘‘
وہ حد درجہ مضطرب اور اس بات پر متاسف تھے کہ انہوں نے خواہ مخواہ ٹینیا کی عصمت کا امتحان کرنا چاہا ہے، لیکن بایں ہمہ وہ اس روز کے منتظر تھے، جب انہیں یہ معلوم ہو جانے والا تھا کہ وہ برتن جس میں انہوں نے اپنے دل رکھے ہوئے ہیں، کتنا صاف اور بے لوث ہے۔ بدقسمتی سے ٹینیا باعصمت ثابت نہیں ہوتی اور وہ سپاہی کے ہتھے چڑھ جاتی ہے۔ یہ داستان خوشگوار نہیں ہے، لیکن گورکی کے قلم نے اسے اس غیر جانبدارانہ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ یہ ہولناک حقیقت معلوم ہوتی ہے۔
’’چھبیس مزدور اور ایک دوشیزہ‘‘ شعریت کی اس قدر زور دار رو سے لبریز ہے، اس میں آزادی اور حسن کا اتنا معتدل ایمان و یقین ہے، اس کے علاوہ یہ داستان اس قدر صحت فن کاری سے بیان کی گئی ہے کہ ہم اسے گورکی کا شاہکار تسلیم کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ افسانہ اسے بلاشک و شبہ ہمارے بلند مرتبت کلاسکس کی صف اولین میں جگہ دلواتا ہے۔‘‘ (پرنس ڈی ایس میرسکی)
اس کا محبوب، جس میں چھبیس مزدور اور ایک دوشیزہ کی روح کارفرما ہے۔ یہ ادب کا ایک درخشاں ٹکڑا ہے جو شعریت، موضوع کی رفعت، تخیل اور صنعت صحیح کے نقطہ نظر سے اپنی قسم کا واحد اضافہ ہے۔ اس میں بدشکل لڑکی کے خیالی محبوب کی تخلیق واقعتاً نادر اور شاندار ہے۔
گورکی اپنے افسانوں میں ارادتاً سوسائٹی کے پائیں طبقے کو زیر قلم رکھتا ہے۔ اس کے کردار بالعموم اپنے مقاصد میں ناکام رہتے ہیں۔ اس کی تمام تر وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جب وہ ایک آوارہ زندگی بسر کر رہا تھا، اسے اسی قسم کے واقعات سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اس کے افسانوں کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں یہ چیز ہر گز فراموش نہ کرنی چاہیئے کہ گورکی کی پرورش آغوش غربت میں ہوئی اور یہ کہ اسے پیٹ پالنے کی خاطر ایک طویل مدت تک ذلیل سے ذلیل مشقت کرنا پڑی۔ اس شخص کے بربط فکر سے جس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ایک تاریک فضا میں اور غیر تربیت یافتہ درشت مزدورں میں بسر کیا، کس قسم کے نغمے بلند ہو سکتے ہیں۔ گورکی ہمیں وہی کچھ پیش کرتا ہے جو اس کے حساس دل نے محسوس کیا اور جو اس کی چشم فکر نے مشاہدہ کیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کا انداز بیان نہایت بیباک اور ’’ظالمانہ‘‘ ہے۔
جس طرح بائرن کا ترنم غیر صناعانہ آتشیں اور آزاد ہے۔ ٹھیک اسی طرح گورکی کی آواز بلندو دیوانہ وار اور بے لگام ہے، جب وہ برہنہ پاوگرسنہ شکم لوگوں کا گیت الاپتا ہے جو اپنی کاہلی پر نازاں ہیں، جو مفلس تو ہیں مگر نڈر، جو اپنی پُر از مصائب زندگی سے خوش ہیں، گو مسرت کے وقت مغموم۔ گورکی کی صدا چیخوف کی شائستہ نرم و نازک اور منجھی ہوئی آواز نہیں، نہ وہ معلم اخلاق تالسٹائی کی کمزور زاہدانہ صدا ہے۔ وہ چنگھاڑتے ہوئے شیر کی گرج ہے۔ چمکتی ہوئی بجلی کی کڑک ہے۔ ابتدائی قوت میں یہ آواز کسی ایسے حساس انسان کی دل میں اتر جانے والی چیخ ہے جس نے زندگی کے مصائب و آلام سہہ کر وہیں دنیا کے منہ پر نہایت بے پروائی سے قے کر دی ہو۔
وہ دنیا جو گورکی اپنے افسانے میں پیش کرتا ہے، ہماری دیکھی بھالی نہیں ہے اور وہ کردار جو اس کے افسانوں کے محرک ہیں، ہم ان سے ناآشنا ہیں، مگر اس کے باوجود کہ ہم اس سرزمین کے جغرافیائی حالات کے سوا کچھ نہیں جانتے، گورکی ہمیں ان گہرائیوں تک لے جاتا ہے اور روسی زندگی کی ایک ایسی قلمی تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے کھینچ دیتا ہے، جس سے عکسی تصاویر عاجز ہیں۔ گورکی کے افسانوں کے کردار عموماً کسان یا مزدور جماعت سے متعلق ہوتے ہیں۔
’’وہ ایسے ناکارہ انسان ہیں جو دنیا کی شاہراہوں پر بھٹک رہے ہوں۔ ان کے ذہن غلاموں ایسے ذہن ہیں۔ کسی آقا یا زندگی کے ایسے قانون کی تلاش جس کی وہ آنکھیں بند کئے اطاعت کر سکیں، ان کا واحد منتہائے مقصد ہوتا ہے۔ ان میں تشخص اور کیریکٹر کی استواری کا فقدان ہے، اگر ان میں الیا لیونیف (7)7 ایسی ہوش مندی اور ذہانت اور اپنی کوششوں سے اپنی حالت کو بہتر بنانے کی صلاحیت ہے تو ان میں نظام خودی کا عنصر بہت قلیل مقدار میں ہوتا ہے جو انجام کار ان کی زندگی کو مغموم بنا دیتا ہے۔ ان تمام امور کے ہوتے ہوئے ان کا خالق یعنی گورکی ان پر ایک غیر معمولی اعتقاد رکھتا ہے۔‘‘ (مس گروسکاٹ)
گورکی کے پروردۂ غربت ہیرو ’’تشخص‘‘ سے بیگانہ ہوں۔ وہ زندگی کی شاہراہوں پر بھٹکے ہوئے ناکارہ انسان ہوں، مگر ان میں ایک نمایاں خصوصیت ضرور ہے، جس کی مثال روسی ادب میں اور کہیں نہیں ملتی۔ وہ دوستو وسکی اور تور گنیف کے پیش کردہ کرداروں کی طرح اپنی تیرہ بختی کا گلہ نہیں کرتے۔ ’’روسی ہیرو‘‘ گورکی اپنے کسی افسانے میں لکھتا ہے، ’’ ہمیشہ جاہل اور سادہ لوح ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ کسی ایسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جس کو وہ سمجھ نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ ملول رہتا ہے۔‘‘
’’ان لوگوں کی زندگی جہالت کا مرقع ہے۔ انہوں نے غلامی کی فضا میں پرورش پائی ہے لیکن وہ یقیناً آزادی کی لذت محسوس کرتے ہیں۔‘‘
’’مجھے اپنی بے خانماں اور آوارہ زندگی پسند ہے۔ بیشتر اوقات سردی نے میری رگوں میں خون منجمد کیا ہے۔ میں نے فاقے کھینچے ہیں، لیکن آزادی عظیم الشان ہے۔‘‘ یہ ہیں وہ لفظ جو ہم گورکی کے ایک کردار کے منہ سے سنتے ہیں۔
دیہات اور شہر کی پرسکون زندگی انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ گورکی کے تقریباً ہر افسانے میں ہم اس کے ’’خانہ بدوش اور حریت پسند کردار‘‘ کو کسی آئیڈیل کا دامن تھامے دیکھتے ہیں۔ یہ خصوصیت بلاشبہ گورکی کا اپنا عکس ہے۔ اس کے کردار عموماً سوسائٹی کے مصنوعی نظام سے رہائی حاصل کر کے نیچر کے وسیع کارخانے میں بھاگ آتے ہیں۔ جہاں انہیں سکونِ قلب اور اطمینان خاطر نصیب ہوتا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ ہم نیچر کو اس کے افکار کے دوش بدوش اور اس کے کرداروں کی انسانی حسیات میں موجود دیکھتے ہیں۔ انسان اور نیچر میں صوفیانہ قربت گورکی کی ہر تصنیف میں بدرجہ اتم موجود ہے، اگر ہم فرداً فرداً اس کے ہر افسانے اور ہر ناول سے اس عنصر کی مثالیں پیش کرنا چاہیں تو اس کے لئے یقیناً ایک علیحدہ مفصل مقالے کی ضرورت ہوگی۔ طوالت کے خوف سے ہم صرف چند مثالوں پر اکتفا کریں گے۔
’’مالوا‘‘ نامی افسانے میں ہم ایک ایسی لڑکی دیکھتے ہیں جو زندگی سے نہ صرف نفرت کا اظہار کرتی ہے بلکہ اس سے سخت اکتا گئی ہے۔ وہ نیچر کے دام الفت میں گرفتار ہے۔ وہ تمام مرد جو اس سے ملتے ہیں، اس کی دلچسپی کا سامان مہیا نہیں کر سکتے۔ اس افسانے کا ایک کردار ان الفاظ میں شہری زندگی سے اپنی انتہائی نفرت کا اظہار کرتا ہے، ’’لوگوں نے شہر اور گھر تعمیر کر رکھے ہیں۔ ان میں بھیڑوں کے گلے کی طرح بسر اوقات کرتے ہیں۔ زمین کو پلید کرتے ہیں، حبس دم ہو رہے ہیں۔۔۔ ایک دوسرے کو دبا رہے ہیں۔۔۔ عجیب مضحکہ خیز زندگی ہے!‘‘
’’میدانوں میں‘‘ نامی افسانے میں گورکی کا خانہ بدوش کردار رات کے وقت زمین پر لیٹا اپنے دوست سے یہ کہتا ہے، ’’یہ زندگی خواہ فاقوں سے لبریز ہے۔۔۔ مگر آزاد ہے۔۔۔ اپنے آقا خود آپ ہو۔۔۔ اگر اپنا سر بھی کاٹنا چاہو تو کوئی روکنے والا نہیں۔۔۔ ان دنوں فاقہ کشی نے مجھے سرکش بنا دیا تھا۔۔۔ مگر میں اب یہاں لیٹا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں۔۔۔ ستارے میری طرف دیکھ دیکھ آنکھیں جھپک رہے ہیں۔۔۔ معلوم ہوتا ہے وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ کیپٹن کچھ فکر نہ کرو۔ جاؤ دنیا کی سیاحت کرو، مگر دیکھو کسی کی غلامی قبول نہ کرنا۔۔۔ دل کس قدر مسرور ہے!‘‘
گورکی کے خانہ بدوش کردار با اخلاص اور بے ریا ہوتے ہیں۔ وہ زبان سے وہی نکالتے ہیں جسے وہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ ان میں تہذیب یافتہ افراد کی بناوٹ اور مداہنت نہیں ہوتی۔ وہ زندگی کو اس شکل میں دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں جیسی وہ اصلاً ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ ظلم کرنے پر بھی اتر آتے ہیں مگر کبھی کبھار۔ ایک اور افسانے میں ہم سوسائٹی کا ایک ایسا کردار دیکھتے ہیں جو کسی تاجر کو قتل کرنے جا رہا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے ایک لڑکی کو دریا میں ڈوبتے دیکھتا ہے مگر اسے صرف اس لئے نہیں بچاتا کہ اسے تاجر کو قتل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس چلکاش عادی چور، شرابی اور آوارہ مزاج اپنے ساتھی گوریلا سے جو ایک کمزور دل دیہاتی ہے، نہایت رحم دلی اور فیاضی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ اسے وہ تمام روپیہ دے دیتا ہے جو اس نے چوری سے پیدا کیا ہوتا ہے۔
ہم گورکی کے افسانوی کردار کی نوعیت پر مختصر تبصرہ کر چکے ہیں۔ آگے چل کر ہم اس کے طویل افسانوں (ناولوں) کے کرداروں پر اس روشنی میں تبصرہ کریں گے۔ گزشتہ اوراق میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ گورکی نے فلسفیانہ گفتگوؤں کو اپنے افسانوں میں داخل کرنا شروع کر دیا جس سے اس کی ادبی شہرت کم ہونے لگی۔ ۱۸۹۷ء میں اس نے ایک افسانہ بعنوان ’’شریر لڑکی‘‘ سپرد قلم کیا۔ اس میں اس نے تعلیم یافتہ لوگوں کی عکاسی کرنا چاہی، مگر اس میں ناکام رہا۔ ہمیں گورکی کے ’’تذکرے‘‘ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے صرف ایسا انشا پرداز بننا ناپسند تھا جس کا خمیر طبقہ ادنی سے اٹھایا گیا۔ وہ فی الحقیقت لیڈر اور معلم کی حیثیت میں خود کو پیش کرنا چاہتا تھا۔ اس خواہش کی جھلکیاں ان ڈراموں اور ناولوں میں صاف طور پر نمایاں ہیں جو اس نے ۱۸۹۹ء کے درمیانی زمانے میں تصنیف کئے۔ اس زمانے کے قابل ذکر ناول یہ ہیں۔
۱۔ فوما گورڈیوف
۲۔ وہ تینوں
۳۔ ماتا
۴۔ ایک
’’فوما گورڈیوف‘‘ عظیم الشان تصنیف ہے۔ اس میں نہ صرف روس کی تمام پہنائیاں مرکوز ہیں بلکہ وسعت زندگی بھی مستور ہے۔ جس طرح کارخانوں اور منڈیوں کی اس دنیا میں اور عبور و مرور اور تجارت کے اس زمانہ میں ہر جگہ غضب ناک لوگ اٹھے ہیں جو ساز حیات کے تاروں میں اس کی صحیح تڑپ کی جستجو کرتے ہیں اور زندگی کی حقیقی تپش سے آشنا ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ’’فوما گورڈیوف‘‘ روس کی سرخ فضا میں ابھرتا ہے اور اسی سوال کا جواب چاہتا ہے۔ اس کتاب میں روسی تجزیہ خودی اور دقیق النظری گورکی ہی کی پیداکردہ ہے۔ اپنے دیگر روسی بھائیوں کی طرح اس کے افکار بھی غیرت مند اور پراز جوش احتجاج کے حامل ہیں، مگر اس احتجاج سے ایک مقصد وابستہ ہے۔ وہ صرف اس لئے اپنا قلم اٹھاتا ہے کہ اسے گوش انسانیت تک کچھ پہنچانا مقصود ہے۔۔۔ اس کے مضطرب بربط فکر سے نرم و نازک راگنیاں بلند نہیں ہوتیں۔ وہ اپنے ساز سے صرف حقیقت کا نغمہ نکالتا ہے۔۔۔ دل سوز، خوفناک اور بے باک!
یہ غلطی ہوگی اگر ہم خیال کریں کہ امراء کی جماعت اس ’’خوف زدہ انسان‘‘ فوما گورڈیوف کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔۔۔ ان کی موٹی کھالوں پر گورڈیوف کی چبھوئی ہوئی سوئیاں کچھ اثر نہیں کر سکتیں۔ انہیں یہ امر نہایت تعجب خیز معلوم ہوگا کہ فوما گورڈیوف نے جسے دولت کی فراوانی اور صحت کی تازگی میسر تھی، اپنے ہم اقتدار لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنا کیوں پسند نہ کیا۔۔۔ ان لوگوں کی طرح جو اپنے وقت کا بیشتر حصہ کرسیوں کے ساتھ چپک کر، تبادلے کے بدلتے ہوئے سودوں کی دھن میں مست اور اپنے حریف ہم پیشہ تاجروں کو کچل ڈالنے کی تدابیر سوچنے میں محو رہتے ہیں۔ فوما گورڈیوف اسی قسم کے ایک تاجر کا لڑکا ہے مگر اس میں بیداری کی چنگاری پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے گردوپیش کی دنیا سے جو تجارت کی ہاؤ ہو سے پر ہوتی ہے، سخت متنفر ہو جاتا ہے۔
’’آہ!‘‘ فوما نہایت گستاخ لہجے میں دریافت کرتا ہے، ’’ اگر زرپرستی کے ان تمام برسوں کا انجام مر جانا اور فنا ہو جانا ہے تو فرمایئے سیم و زر کی اس ہوس سے فائدہ؟‘‘ جس سرمایہ دار سے فوما نے یہ’’ گستاخانہ‘‘ سوال کیا، وہ اسے سمجھنے سے قاصر تھا۔ خود میاکن (فوما کا روحانی باپ) بھی اپنے روحانی بیٹے کو نہ سمجھ سکا۔
’’آپ فخر کیوں کرتے ہیں؟‘‘ ایک روز فوما، میاکن پر برس پڑتا ہے، ’’آخر آپ اترا کس چیز پر رہے ہیں۔۔۔؟ آپ کا لڑکا بتایئے وہ کہاں ہے۔۔۔؟ آپ کی لڑکی، فرمایئے وہ کیا ہوئی۔۔۔؟ زندگی کے ناظم صاحب، مانا کہ آپ چالاک ہیں۔ آپ کے علم میں سبھی کچھ ہے، مگر ذرا یہ تو بتایئے، آپ کس لئے جیتے ہیں؟ روپیہ کیوں اکٹھا کرتے ہیں۔۔۔؟ کیا آپ کو مرنا نہیں ہے۔۔۔؟ تو پھر؟‘‘
میاکن کے پاس ان تمام سوالوں کا جواب نہیں ہوتا، مگر وہ پھر بھی اپنی ہٹ پر قائم رہتا ہے۔ فوما گورڈیوف کے سوالات غیر متوقع اور تیز ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں اس کے مضطرب قلب کی آئینہ دار ہیں۔ دراصل وہ اپنے دل میں ایک عجیب قسم کی بے چینی محسوس کرتا ہے۔ جب وہ اپنے ماحول میں ہر چیز کو انسانیت کش پاتا ہے، یہ اضطراب یہ بے قراری اس کی زبان پر چند پریشان مگر آتشیں الفاظ لاتی ہے، وہ ہر اس شخص کے منہ پر کہہ ڈالتا ہے جو اس سے ہم کلام ہو۔ فوما گورڈیوف اس ماحول سے باغی ہو جاتا ہے، جو سراسر دولت کمانے کی خود غرض خواہشات اور نفس دوستیوں سے لبریز ہے۔ اگناٹ (فوما کا باپ) میاکن (فوما کا روحانی باپ) اور اسی قسم کے دیگر کامیاب تاجروں کے طلائی سکوں کی تعریف میں گائے ہوئے گیت اس پر اثر انداز نہیں ہوتے۔
’’ یہ لوگ کیوں گائیں، جب پاس ہی دوسرے رو رہے ہیں۔۔۔؟ یہ زندگی ایک کابوس ہے۔۔۔! خواب جس کا کوئی مطلب نہیں! میں پوچھتا ہوں اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے نیچے کیا ہے؟‘‘
اگناٹ، فوما کو جو ابھی کم سن لڑکا ہوتا ہے، سمجھاتا ہے، ’’اگر تم غربا کو ہمدردی کی نگاہوں سے دیکھتے ہو تو یہ ایک نہایت مبارک جذبہ ہے، لیکن تمہیں اپنی اس ہمدردی کے ساتھ انصاف برتنا چاہیئے۔ اولاً تمہارے پیش نظر یہ ہونا چاہیئے کہ وہ شخص جسے تم ہمدردی کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو اس کا مستحق بھی ہے یا نہیں، اگر یہ شخص اہلیتوں اور طاقت کا مالک ہے اور تمہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی امید ہو سکتی ہے تو تم بخوشی اس کی مدد کرو، لیکن اگر وہ کمزور ہے، کام کرنے کے ناقابل ہے تو اس پر تھوک دو اور اپنے مطلب سے غرض رکھو۔ یہ بھی واضح رہے کہ وہ شخص جو ہر چیز کے متعلق شکوے شکایت کرتا رہے اور ہر وقت اپنا رونا روتا رہے، ایک پھوٹی کوڑی کا حق دار نہیں ہے۔۔۔ ایسے شخص کی مدد کرنا بے کار ہے۔‘‘
باپ کی ان زرگرانہ اور تاجرانہ نصیحتوں کے باوجود فوما اپنی دھن میں مست رہا۔۔۔ ان پند و نصائح نے احساس بیداری کی اس چنگاری کو ہوا دے کر شعلوں میں تبدیل کر دیا جو اس کے نوخیز دماغ میں سلگ رہی تھی۔ میاکن فوما کا روحانی باپ الگ اپنا زاہدانہ راگ الاپتا ہے۔ وہ یہ وعظ کرتا ہے، ’’میرے عزیز، معلوم ہے بھکاری کیا ہوتا ہے؟ بھکاری وہ انسان ہے جسے قسمت مجبور کرتی ہے کہ وہ ہمیں حضرت عیسیٰ ؑ کی یاد دلائے۔ وہ عیسیٰ کا بھائی ہے۔۔۔ خدا کا گجر جو ہمارے خوابیدہ ضمیر کو بیدار کرنے کے لئے فضا میں گونجتا ہے۔ وہ کھڑکی کے نیچے کھڑا ہو کر گاتا ہے۔ عیسیٰ کی راہ میں۔ اس صدا سے وہ ہمیں مقدس پیغمبر کے احکام کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ہمیں غربا کی مدد کرنی چاہیئے، مگر مقام تاسف ہے کہ فی زمانہ لوگ اپنی زندگی کچھ ایسے طریق پر گزار رہے ہیں کہ اس کی تعمیل محال ہے۔۔۔ اب ہم ان تمام فقیروں اور گداگروں کو ایسی چار دیواری میں قید کر دینا چاہتے ہیں کہ وہاں سے نکل کر وہ ہمارے ضمیر کو نیک کام کے لئے بیدار نہ کر سکیں۔‘‘
فوما کے دماغ پر ا ن تمام کی گفتگوؤں کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔۔۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی چیخ ان خشک و تر نصیحتوں کی طالب نہیں ہوتی۔ فوما روشنی چاہتا ہے اور چونکہ روشنی ڈھونڈنے کی یہ خواہش اسے ایک لمحہ چین نہیں لینے دیتی۔ ا س لئے وہ اپنے بغاوت سے بھرے ہوئے سینے کو لے کر اٹھتا ہے اور زندگی کے حقیقی معانی کی جستجو کرتا ہے۔
’’اس کے تمام خیالات اس غلیظ جماعت پر مرکوز ہو گئے جو صبح سے شام تک گدھوں ایسی مشقت کرتی تھی۔۔۔ یہ منظر اس کے لئے سخت تعجب افزا تھا۔۔۔ اسے حیرت تھی کہ وہ زندہ کیوں ہیں؟ انہیں اپنے تاریک ماحول میں ایسی کون سی شعاع نظر آئی ہے جس کے سہارے وہ جی رہے ہیں؟ ان کا کام صرف اپنے غلیظ فرائض کو سرانجام دینا اور کڑی سے کڑی مشقت کرنا تھا۔ ان کے بدن پر چیتھڑے لٹک رہے ہوتے۔ وہ سوکھی روٹی پر گزرا وقات کرتے اور ان میں سے اکثر شراب کے عادی ہوتے۔۔۔ اگر کسی کی عمر ساٹھ سال سے تجاوز کر گئی ہوتی تو اس ضعیف العمری کے باوجود وہ نوجوانوں کے دوش بدوش مشقت میں مصروف نظر آتا۔۔۔ یہ تمام مزدور فوما کی نظر میں کیڑوں کا ایک ڈھیر تھا جو زمین پر کچھ کھانے کے لئے رینگ رہے ہوں۔‘‘
رفتہ رفتہ فوما زندگی کا ایک مجسم استفہام بن جاتا ہے۔ وہ زندہ رہنے سے منکر ہو جاتا ہے۔ جب تک اسے زندگی کا اصل مطلب سمجھ نہ آ جائے، ’’میں کیوں زندہ رہوں۔ جب مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ اس زندگی کا مطلب کیا ہے؟‘‘ وہ ایک بار میاکن سے دفعتاً سوال کرتا ہے جو اسے اپنے مرحوم باپ کا کاروبار سنبھالنے کے لئے کہہ رہا ہوتا ہے۔ دراصل فوما کی عقل اس عقدے کو حل کرنے سے قاصر ہوتی ہے کہ لوگ صرف اس کی واحد ذات کے لئے کیوں مشقت برداشت کریں اور اس کے اور اس کی دولت کے غلام بنیں؟
’’انسان کے لئے مشقت ہی میں تمام نعمتیں نہیں دھری ہیں۔۔۔ کام کے ساتھ اس عذر کو وابستہ کرنا غلطی ہے۔ بعض افراد ایسے بھی ہیں جن کے ہاتھ محنت و مشقت سے ناآشنا ہیں لیکن بایں ہمہ وہ نہایت شاندار زندگی بسر کرتے یں۔ اس کی وجہ؟ میرے پاس پر از عیش زندگی بسر کرنے کا کیا عذر ہے؟ وہ لوگ جو دوسروں سے اپنے احکام منواتے ہیں، آرام دہ زندگی بسر کرنے کا کیا حق رکھتے ہیں؟ وہ کس لئے زندہ رہتے ہیں؟ میرا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کو چا ہئے کہ وہ زندگی شروع کرنے سے پیشتر قطعی طور پر معلوم کر لے کہ وہ کس مقصد کے لئے زندہ رہنا چاہتا ہے۔۔۔ کیا یہ ممکن ہے کہ زندگی کا مقصد مشقت، روپیہ کی فراہمی، مکانوں کی تعمیر، بچوں کا پیدا کرنا اور مرجانا ہے؟ ہر گز نہیں۔۔۔ مقصد حیات کچھ اور ہے۔۔۔ انسان پیدا ہوتا ہے۔ کچھ مدت کے لئے زندہ رہتا ہے اور مر جاتا ہے۔۔۔ کتنی مضحکہ بات ہے؟ ہم سب کو یہ سوچنا سزا وارہے کہ زندگی کس لئے عطا کی گئی ہے۔۔۔ خدا کی قسم۔۔۔ اس کا صحیح جواب سوچنا ہر انسان کا فرض ہے۔ ہماری یہ زندگی فضول ہے، لایعنی ہے۔۔۔ بیہودہ ہے۔ بکواس ہے! کچھ امیر ہیں جن کے پاس اس قدر دولت ہے کہ وہ ہزاروں انسانوں کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں۔۔۔ وہ بالکل ہاتھ پیر نہیں ہلاتے۔ دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو تمام عمر مشقت میں اپنی کمریں دوہری کر لیتے ہیں، مگر ان کی جیبیں تانبے کے ایک پیسے سے ناآشنا رہتی ہیں۔‘‘
فوما کو جس طرف روشنی کی مدھم شعاع بھی نظر آتی ہے، وہ ادھر دوڑ پڑتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ ہر چیز سقیم ہے، مگر وہ اس سقم کو دور کرنے کی قدرت خود میں نہیں پاتا۔ وہ صرف حملہ کرنا اور تباہ کرنا جانتا ہے۔ وہ تاجروں کی بہرہ مند ہستیوں سے سوال کرتا ہے، ’’ یہ زندگی تمہاری تخلیق کردہ نہیں۔۔۔ تم لوگوں نے اس دنیا کو گندگی کا ایک عمیق گڑھا بنا رکھا ہے۔ تمہارے افعال غلاظت افشانی کرتے ہیں۔ کیا تم اپنے پہلو میں ضمیر رکھتے ہو؟ کیا خدا کی یاد تمہارے دلوں میں موجود ہے؟ پانچ دمڑی کا پیسہ۔۔۔ یہ ہے تمہارا معبود!‘‘
اور پھر عیسیٰ کی روحانی آواز کی طرح وہ ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ’’اے زردارو! ان قہروں پر آنسو بہاؤ جو عنقریب تم پر برپا ہونے والے ہیں۔۔۔ خون چوسنے والے پسوو! تم دوسروں کی طاقت کے بل بوتے پر جیتے ہو۔ تم مستعار ہاتھوں سے کام کرتے ہو۔۔۔ تم تباہ ہو جاؤ گے۔۔۔ تمہیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔۔۔ آنسو کے ننھے قطرے تک کا۔‘‘
وہ اپنے گردوبیش کی تاریکی سے متعجب ہو کر سوال کرتا ہے اور سوال کئے جاتا ہے کہ اسے اسرار کا کوئی حل مل سکے مگر بے سود، چنانچہ وہ زندگی کی بھول بھلیوں میں ٹھوکریں کھاتا، موت کا ناچ ناچتا، کسی موہوم چیز کی تلاش میں سرگرداں اور زندگی کے صحیح مقصد کی جستجو میں حیران رہتا ہے اور انجام کار پاگل ہو جاتا ہے۔
یہ کتاب دل کش نہیں ہے، مگر عبارت ہے زندگی کے استفہام سے۔۔۔ عمومی زندگی سے نہیں بلکہ آج کل کی معاشرتی زندگی سے۔۔۔ یہ کتاب پرلطف نہیں۔ ا س لئے کہ موجودہ معاشرت پرلطف نہیں ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد قاری دنیا کی ابلہ فریبیوں اور دروغ کاریوں سے آشنا ہو کر زندگی سے متنفر ہو جاتا ہے۔۔۔ مگر بایں ہمہ یہ تصنیف صحت بخش ہے۔ اس کے اوراق میں معاشرتی مرض کی ایسی حکیمانہ تشریح کی گئی ہے اور معائب کا تاروپود اس بے دردی سے بکھیرا گیا ہے کہ اس کا وجود سوائے انسانی فلاح کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔
۱۹۰۵ء کے انقلاب کے بعد گورکی کی جوئے فکر ایک تندوتیز سمندر کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ وہ اب دنیا کا نہایت متانت سے مطالعہ کرنے کے بعد نظام حیات کی پہنائیوں تک پہنچتا ہے کہ اپنے پیش نظر مقاصد کی تخلیق و تولید کرے۔ ان کتابوں میں جو گورکی نے اس زمانے میں سپرد قلم کیں، ’’ماتا‘‘ سب سے مشہور ہے۔ یہ کتاب جو روسی انقلاب کے زیراثر لکھی گئی۔ انقلابی تحریک کی نہایت واضح تصاویر پیش کرتی ہے۔ ہم یہاں اس پر مختصر تبصرہ کرتے ہیں،
بیسویں صدی کے آخری نصف میں روس کو ایک نمایاں جگہ حاصل ہے، جس طرح زمین کا یہ خطہ نقشہ عالم پر پھیلا ہوا ہے، ٹھیک اسی طرح ملت روس کی جدوجہد آزادی کے خونی واقعات تاریخ عالم کے بیشتر اوراق گھیرے ہوئے ہیں۔۔۔ شائد ہی چشم قمر نے ایسے لرزہ خیز وقائع و مناظر، دل ہلا دینے والے ستم وجور، خوفناک جرائم اور جنگ آزادی میں خون کے ایسے دریا بہتے ہوں گے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم انسانی زندگی کو ایک ڈرامہ خیال کرتے ہیں تو اس عظیم ڈرامے کی اور کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی جو روس کی سرخ اسٹیج پر کھیلا گیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم بہادری کے ان کارناموں، قربانیوں اور شجاعتوں سے سے متاثر ہوتے ہیں، جو کسی نیک مقصد کے لئے عمل میں لائی گئی ہیں تو روس کی اس آزادی کی کشمکش کا اور کون مدمقابل ٹھہر سکتا ہے۔
اگر یہ کہا جائے کہ ہم ان جواں مردوں، بزرگوں، ولیوں اور شہیدوں کا شمار کرنے کے بعد جنہوں نے قصر آزادی کی تعمیر میں حصہ لیا، کسی قوم کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو ملت احمر کے ان برہنہ پا مرد اور عورتوں کی مثال موجود ہے، جنہوں نے ایوان جمہوریت کی تاسیس کے لئے اپنے خون اور گوشت پوست کو پیش کر دیا۔ بدیسی غلامی کو اپنی سعادت اور اس دیوی کی پوجا کرنا اپنا فرض واحد خیال کرتے تھے۔ وہ اپنے جان و مال کو زار کی ملک سمجھتے تھے۔
بادشاہ کا ہر لفظ لفظ الٰہی تھا۔ اس کے قلم کی ہر جنبش فرمان ربانی!
زار روسیوں کے لئے خدا کا سایہ اور باپ تھا۔
اس کے ڈھائے ہوئے مظالم عوام کے لئے شہد کی طرح شیریں تھے۔
روسی قوم کسی تاریک خواب میں مدہوش پڑی تھی!
آخرش کیا ہوا؟
کورنش بجا لانے والے ہاتھ ستم ورانہ اٹھے اور زار کو اس کے تخت سے نیچے گھسیٹنے لگے۔
ٹھوکریں کھائے ہوئے سینے ابھرے اور زار کی مطلق العنانی کے مقابل آہنی دیوار بن گئے۔
بادشاہ کے ڈھائے ہوئے تلخ مصائب کو عوام نے اسی کے منہ پر تھوکنا شروع کر دیا!
جرس انقلاب کا بے پناہ شور بلند ہوا اور قانون کی بلند آہنگی کو ہمیشہ کے لئے اپنی آغوش میں سمیٹنا شروع کر دیا!
پھر اسی خوشگوار باد نسیم کے راندے ہوئے لوگوں پر جنت ارضی کے تمام دروازے نیم وا ہونے لگے۔
ماتا اسی زمانے کی ایک داستان ہے، جب جنگ آزادی کی تڑپ ہر نوجوان کے قلب کو گرمائے ہوئے تھی۔ اس خونچکاں کہانی میں ملت احمر کے مایہ ناز مفکر گورکی نے اس خونی جدوجہد کی اس کامیابی و فن کاری سے تصاویر کھینچی ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ واقعہ ہو بہو رقص کرتا نظر آتا ہے۔ دراصل روس کے یہاں ہر چیز ایک عظیم پیمانے پر ہے۔ اس کے افسانہ نگاروں کی کہانیاں مینڈک کے پاؤں کی ان بڑی تصاویر کی مانند ہوتی ہیں جو کسی طبی اسکول کے کمرے میں پردہ سیمیں پر دکھلائی جا رہی ہوں۔ ان تصاویر کے ذریعے سے ہم دلوں میں دوڑتا ہوا خون، حرکت کرتی ہوئی نسیں اور پراسرار نظام عصبی کو جو اس سے پیشتر ہماری آنکھوں سے نہاں تھا، بخوبی مشاہدہ کر سکتے ہیں، ٹھیک اسی طرح کے جذبات و حسیات جو اس سے قبل صرف ہماری سماعت تک محدود تھے، گورکی کے بیان کردہ واقعات سے ہم پرروشن ہو جاتے ہیں۔
مے خانوں میں خفیہ ملاقاتیں، سرگوشیوں میں تباہ کن سازشوں کی تیاری، رات کی تیاری میں خنجر کی جھلک، منڈلاتے ہوئے جاسوس، مصائب و نوائب کے تیروں سے چھلنی دل، گلی کوچوں میں صدائے انتقام، خون کی ندیاں، غیر مختتم غم واندوہ، لامتناہی سیل عشق اور برہنہ پا وگر سنہ شکم انسانوں کی خون منجمد کر دینے والی برف باری میں حسرت ناک اموات ہماری آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہوتی نظر آتی ہیں۔
روسی تندخو بھی ہیں اور نرم مزاج بھی۔ ظالم بھی ہیں اور رحم دل بھی۔ نفرت بھی کرتے ہیں اور پیار بھی۔ جاہل بھی ہیں اور عالم بھی۔ بے وقوف بھی ہیں اور چالاک بھی۔ بادشاہت کے حامی بھی ہیں اور آزادی کے دلدادہ بھی۔ غیر حساس بھی ہیں اور حساس بھی۔ بھولے بھی ہیں اور زمانہ ساز بھی۔ سب سے زیادہ جذباتی بھی ہیں، مگر سب سے زیادہ دبے ہوئے بھی ہیں۔ ان سب کے علاوہ ان میں محسوس کرنے کا مادہ اپنی ہمسایہ قوموں سے کہیں زیادہ ہے اور غالباً یہی ان کے تصور نما افکار کا سب سے بڑا راز ہے، جسے دیکھ کر دنیا آنکھیں جھپکتی رہ گئی ہے۔ افسانہ نگاری میں ان کا ناقابل نقل فن کسی اور دماغ کے بس کا نہیں ہے۔
روس کے ان تمام مفکروں اور ان کی تمام تصانیف میں سے جو انسانی قلوب پر اثر انداز ہوتی ہیں، بلاشک و شبہ گورکی سب سے بڑا مفکر اور اس کا شاہکار ’’ماتا‘‘ (مدر) سب سے اعلیٰ تصنیف ہے۔ کوئی دوسرا انشا پرداز یا افسانہ نگار ان واقعات کا صرف ہلکا سا خاکہ کھینچ کر بس کر دیتا جو فضا میں ٹھوس چٹانوں کی مانند کھڑے تھے، مگر گورکی کا قلم اس ٹھوس موضوع پر شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی روانی سے چلا ہے اور اس دوران میں اس کی فن کاری میں کسی مقام پر بھی لغزش نہیں آنے پائی۔ زندگی کے اس پیش نظر ٹکڑے کو جس پر وہ اپنے لاثانی افسانے کی چار دیواری بلند کرنا چاہتا ہے، وہ کسی ماہر معمار کی طرح ہر پہلو سے بغور دیکھتا ہے تاکہ عمارت میں کوئی خامی نہ رہ جائے۔
گورکی یہ افسانہ لکھنے سے پیشتر چاروں طرف نگاہ دوڑا کر حقیر سے حقیر واقعات کو بھی فراہم کر لیتا ہے کہ شاید وہ کسی جگہ کے لئے موزوں ہوں۔ شوربے کی تلخی، مرد کے بوٹ سے چمٹی ہوئی برف، کسی عورت کے بالوں میں اٹکے ہوئے برف کے گالے، لکڑیاں کاٹتا ہوا لکڑ ہارا، دہقانوں کی بھدی گفتگو، پیانو کے چھیڑے ہوئے نغمے، سنتری کی آنکھوں میں حیوانی جھلک، بازاروں میں اڑتی ہوئی کیچڑ اور کارخانوں کے بلند دود کشوں کا سیاہ دھواں۔۔۔ ان تمام کم حقیقت اور مہمل چیزوں کے اجتماع سے اس کا دست فکر ایسے مناظر پیش کرتا ہے جو اپنے اندر اثر پیدا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔
گورکی کے یہ افکار ہمارے دل و دماغ کو چیرتے ہوئے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ فلمی تصاویر جو اس نے ایک مرقع میں جا بجا چپکا دی ہیں، احساسات کی ان عمیق گہرائیوں میں لے جاتی ہیں، جن سے رومانی افسانے اور عکسی تصاویر عاجز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے اذہان میں حقیقی زندگی کا انجکشن کر دیا ہے۔ یہ جدا امر ہے کہ ہم اس کی بیان کردہ داستان کے محل وقوع کی سرزمین سے واقف نہیں، مگر اس نے ہمارے سامنے روسی زندگی ایسے صاف و عیاں طور پر پیش کی ہے کہ اب ہمیں مزید مطالعہ یا مشاہدہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ گورکی کا فقید المثال اور پراسرار فن اسی میں مضمر ہے کہ وہ اپنے قلم کی سیدھی سادی جنبشوں سے ہم پر دہقان کی جھونپڑی کا منظر، سرما کی خون منجمد کر دینے والی سردی اور گاؤں کے نیم برہنہ لوگوں کی ٹھیرے پانی ایسی زندگی اور کھنڈروں میں انسانی ارواح کی کشمکش کی صحیح کیفیت طاری کر دیتا ہے۔۔۔ اس کے علاوہ آرٹ کا مقصد ہو بھی کیا سکتا ہے!
روس کے تمام ڈراموں میں جو عمومی زندگی سے متعلق ہیں، یہ تمثیل سب سے نمایاں رتبہ رکھتی ہے۔ جس میں پرانے نظام کو پاش پاش کرنے کے لئے ایک طویل جنگ مدت تک کروٹیں لیتی رہی ہے۔ کم و بیش ایک سو سال تک روسی لوگ جیلوں کو آباد کرتے رہے۔ مقننین اور جلّادوں کو مشغول رکھا۔ سائیبریا کے یخ بستہ میدانوں میں منجمد ہونا قبول کیا اور حکام کو خطرے کی گھنٹیاں بجا بجا کر جھنجھوڑتے رہے۔ جب ہمیں یہ حقیقت معلوم ہے کہ ستر سال کے دوران میں آٹھ لاکھ سے کچھ زیادہ سیاسی اسیر عدالت کے ایک دروازہ سے سائبیریا میں دھکیل دیے گئے تھے تو وہ واقعات جن کی گورکی نقاب کشائی کرتا ہے، بعید از فہم معلوم نہیں ہوتے۔
در اصل روس کی یہ جنگ آزادی اپنی مثال نہیں رکھتی۔ جمہوری حکومت کے لئے اٹلی کی پچاس سالہ کشمکش کو ابھی اس پر وقعت نہیں دی جا سکتی۔ ہر سال ہزاروں روسی عورتیں اور مرد پڑھتے اور جلاوطن اور مرے ہوئے لوگوں کی خالی جگہ پر کر دیتے۔ یہ جان نثار لوگ اس وقت تک دم نہ لیتے، جب تک حکومت کے بھیانک نظام کی سرد انگلیاں ان کا گلا نہ دبا دیتیں، میدان جنگ میں سربکف نکلنا اس وقت واقعی معنی رکھتا ہے، جب دونوں فریق ہم پلہ ہوں۔ زندگی اور فتح کا ایک موقع ہو۔ اس صورت میں مادر وطن کے ہر فرد کی زندگی کی رگ میں خون جوش سے ابلنے لگتا ہے۔ خطرہ کا خوف غائب ہو جاتا ہے اور قربانیوں کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ مگر غیر مرئی خاموش عیار اور خونی قاتلوں سے تاریکی کے پردے میں جنگ کئے جانا ہمیشہ اپنی جان ہی کے خطرے کا احتمال ہونا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کشمکش کا انجام یقینی موت ہے اور پھر اس انجام کو بے دھڑک قبول کر لینا، ایسی ہمت و جواں مردی ہے جو آج تک کوئی قوم نہیں دکھا سکی۔
روز بروز روس دیگر ممالک کی عنان توجہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور ابھی کافی مدت تک اپنی معاشرتی سیاسی اور ادبی تحریکات کی وجہ سے کھینچتا رہے گا۔ موجودہ روس کو وہ شخص ہر گز اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا، جو پرانے روس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ روس کی جدوجہد آزادی کے زمانے پر روشنی ڈالنے کے لئے صرف گورکی کا چراغ فکر ہی سب سے زیادہ تاباں ہے۔ وہ واقعات جنہیں قلم بند کرنے کے لئے ایک فلسفہ دان اور مؤرخ سالہاسال کی طویل کوشش کے باوجود بھی ناکام رہتا، گورکی کی ’’ماتا‘‘ نے چند مختصر ابواب میں بیان کر دیا ہے۔ جب اس داستان کا مطالعہ کیا جائے تو روس روشنی میں نظر آتا ہے۔
زندگی جیسی ہے نہ کہ جیسی ہو سکتی ہے۔ خیال کی جا سکتی ہے یا ہوگی۔ یہ ہے گورکی کا فن اور یہی ہے روس کے دیگر افسانہ نگاروں کا راز!نقلی مہیج، نقلی انسانیت یا نقلی زندگی کے نقلی نقشوں سے روسی افسانہ نگاروں کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کے نزدیک صرف کہانی کا ڈھانچہ خیالی ہو سکتا ہے اور بس! باقی افسانے کے سب کردار حقیقی ہونے لازمی ہیں۔
انسان کو بیک وقت حسین، جواں مرد اور چالاک شیطان پیش کرنا ان کے نزدیک فن صحیح و صنعتِ سنجیدہ ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ وہ مغربی افکار کے طومار کو بنظر استحسان نہیں دیکھتے۔ پریوں، دیوؤں، ناقابل فہم نوجوانوں اور لڑکیوں کی کہانیاں ان کی نظروں میں بالکل مہمل نظر آتی ہیں۔ وہ اسے بخوبی سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات پردہ ظہور پر ہر گز نہیں آتے۔ مغربی کرداروں کی صفحات پر تھکا دینے والی بھاگ دوڑ کو وہ بچوں کا ایک کھیل خیال کرتے ہیں۔۔۔ وہ سخت حیران ہیں کہ مغربی اذہان کب اس خواب سے بیدار ہوں گے۔
گورکی کی قوت بیان کو سمجھنے کی خاطر اس فرق کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔۔۔ اس کی تصانیف میں اس کے کردار بظاہر بالکل بے معنی سی باتیں کرتے ہیں۔ اس لئے کہ انسانی گفتگو ننانوے فیصد اسی قسم کی ہوتی ہیں۔ اس کے بیان کردہ لوگ عجیب عجیب حرکات کرتے ہیں۔ بہت جلد آگ بھبھوکا ہو جاتے ہیں۔ بغیر کسی وجہ کے فوراً ہی ان کا غصہ سرد ہو جاتا ہے۔ ان کی سرگرمیوں کا آغاز و انجام واقعات کی رفتار پر انحصار رکھتا ہے اور وہ اس دوران میں مقدر کے انتخاب کردہ ہتھیاروں کا کام دیتے ہیں۔ اس لئے کہ حیات حقیقی میں ان کا یہی حصہ ہے۔
یہ حقائق گورکی کے قلم سے اس انداز میں بیان کئے جاتے ہیں کہ ہماری نظروں کے سامنے وہ تاریک، بھیانک، بے رحم، کو رچشم اور خون میں لتھڑی ہوئی مشین واضح طور پر حرکت کرنے لگتی ہے جو روس پر حکومت کر رہی تھی۔ گورکی نے نہ صرف یہی کچھ کیا ہے بلکہ ہمارے جسم پر اس خوف کی کپکپی بھی طاری کر دی ہے۔ اس کی یہ تصنیف مطالعہ کرنے کے بعد ہم اس آہنی دیو کی گرفت محسوس کرتے ہیں جو اس زمانے میں سرزمین روس پر ڈکار رہا تھا۔
اس طرح گورکی ہماری حیرت زدہ آنکھوں کے سامنے اپنے خوفناک نظام کی، جس کی گرفت سے کوئی بھی رہائی نہیں پا سکتا، اس مرد کی جو اپنے مصائب کو فراموش کرنے کی دوا کو شراب خیال کر کے پیتا حیوان بن جاتا ہے اور اس دیوانگی کی حالت میں اپنی بیوی کو زد و کوب کرتا ہے اور اس نوجوان کی جو ایک کتاب میں دنیائے آزادی کی جھلکیاں دیکھ کر خود کو دہکتے ہوئے الاؤ میں گرا دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ دیو جس سے وہ برسرپیکار ہے، کس آسانی سے اس کا غنچہ حیات اپنے ہاتھوں سے مسل سکتا ہے، حکایت پیش کرتا ہے۔ طبقہ اعلیٰ کے اس فرد کا افسانہ جو خطرناک مواقع کی نبض گرتی دیکھ کر انقلاب پسند جماعت کا رکن بن جاتا ہے، ناز و نعمت میں پلی ہوئی ان عورتوں کی داستان جو بغیر کسی حیل و حجت کے کشمکش آزادی میں مردوں کے دوش بدوش حصہ لیتی ہیں، خواہ انہیں کیسے ہی لرزہ خیز مصائب سے کیوں نہ سامنا کرنا پڑے، تپ دق کے ایک خون تھوکنے والے مریض کے ایثار کا واقعہ جو اس جد و جہد میں تادم آخر حصہ لیتا ہے، کمال فن کاری سے بیان کرتا ہے۔
ایک نوجوان اور دوشیزہ محبت میں گرفتار ہیں۔ وہ شادی کے خیال کو بالائے طاق رکھ کر جنگ آزادی میں شامل ہو جاتے ہیں۔۔۔ ا س لئے کہ محبت ان کے نیک مقصد میں حارج ہے۔ ایک تعلیم یافتہ مطالعہ کتب، موسیقی اور امن کا دلدادہ ہے، وہ ان کو فراموش کر دیتا ہے۔۔۔ اس لئے کہ اس کی جد و جہد آزادی میں یہ چیزیں مخل ہیں، پھر اسی تعلیم یافتہ مرد کی نوجوان بہن اپنے خوش نما لباسوں اور پرتکلف بچھونوں کو ٹھکرا کر انقلاب پسند جماعت میں ایک قلی کے فرائض انجام دیتی ہے۔
ایک پراز مسرت ہنسی کے ساتھ صوفیہ نے ماتا کو اپنی انقلابی سرگرمیوں کا حال سنانا شروع کیا۔ جیسے وہ بچپن کی خوشگوار داستان ہو۔ صوفیہ کو اپنا نام تبدیل کرنا پڑا تھا۔ جاسوسوں کی تیز نگاہ سے بچنے کے لئے مختلف بھیس بدلنے پڑے تھے۔ ہزاروں من وزنی انقلابی کاغذات ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کرنا پڑے تھے اور اپنے رفیقوں کی رہائی کے لئے بیسیوں تدابیر عمل میں لانا پڑی تھیں۔ اس کے پاس کاغذات چھاپنے کے لئے ایک چھوٹا سا پریس بھی تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ سپاہی تلاشی کے لئے باہر دروازے پر کھڑے ہیں تو اس نے ان کے اندر داخل ہونے سے ایک لمحہ پہلے خادمہ کا لباس پہنا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ انہیں راستے میں ملی۔ چہرے پر صرف ایک ہلکی سی نقاب تھی۔ سر پر اس نے چھوٹا سا رومال اوڑھ رکھا تھا۔ ہاتھ میں مٹی کے تیل کا بھبھکا تھا۔ اس حالت میں وہ مکمل ایک دن سرما کی بے پناہ سردی میں شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چکر لگاتی رہی تھی۔
اسی طرح ایک دفعہ اور یہ واقعہ ہوا تھا۔ وہ ابھی ایک غیر مانوس شہر میں چند رفیقوں کی ملاقات کے لئے پہنچ کر ان کے مکان کی سیڑھیاں ہی چڑھ رہی تھی کہ اسے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کی تلاشی ہو رہی ہے۔ بھاگنا فضول تھا۔ اس لئے اس نے بغیر کسی تامل کے درمیانی چھت کے ایک دروازے کی گھنٹی دبا دی اور دروازہ کھول کر ان نامعلوم اشخاص کے پاس چلی گئی جن سے وہ قطعاً ناواقف تھی اور اپنی موجودہ حالت صاف صاف بیان کر دی، ’’اگر آپ چاہیں تو مجھے سپاہیوں کے حوالے کر سکتے ہیں، مگر مجھے امید نہیں کہ آپ ایسا کریں گے۔‘‘
ایسے مرد اور عورتوں کے حالات پڑھ لینا ہی کافی ہے، مگر ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، سمجھنا، سننا، ان کے کام کا مشاہدہ کرنا اور ننگے ہاتھوں سے مطلق العنانی کی ان سیسہ پلائی ہوئی خونی دیواروں کو منہدم کرنے کی سعی کرتے دیکھنا جو روس کے کمزور و نحیف سینے پر سوار تھیں، زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔۔۔ یہ سب مناظر گورکی اپنے قلم کی ایک جنبش ہی سے ہم پر واضح کر دیتا ہے اور اس کی اس تصنیف کے اوراق پر پھیلا ہوا سحر ابھر ابھر کر ہمیں بالشوزم کے اسرار بتاتا ہے۔
ان مناظر میں ہم ایک بوڑھی عورت دیکھتے ہیں، جو اس افسانے کی روح رواں ہے۔ یہ عورت (ماتا) عمر رسیدہ ہے۔ ایک خاص شب تک وہ اسی مہلک نظام کے لاکھوں گونگے شکاروں میں سے تھی۔ کمال صبر سے اپنے خاوند کی مار پیٹ سہتی تھی۔ اس کی کتاب حیات میں ہر نیا باب اس امید کا حامل تھا کہ شاید وہ اپنے خاوند کی زدوکوب سے بچ جائے۔ اپنی ہڈیوں میں حیوانی زندگی کو برقرار رکھنا ہی اس کی واحد خواہش تھی۔ پھر ہم کیا دیکھتے ہیں۔۔۔؟ گورکی کا سحر آفرین قلم اسی ایک عورت میں تمام روس کو پیش کر دیتا ہے۔ بغاوت کا احساس اولیں اسے خوف زدہ کر دیتا ہے۔ وہ خیال کرتی ہے۔ کیا؟ زار کے خلاف نبرد آزمائی۔۔۔ اسرائیلی قوم کے مقدس فرد سے جنگ، آسمانی حکم سے بیگانگی، جس نے یہ تاج پوش شیطان ان کی گردنوں پر مسلط کر دیا ہے؟
مگر یہ خیال تبدیل ہو جاتا ہے! وہ دلکش، جان پرور اور عجیب خوابوں کے قریب پہنچ کر انہیں پسند کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ان میں حصہ لینا چاہتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عورت ایسے صبر آزما، پر از شجاعت کام کرتی ہے، جن کے لئے دلیری درکار ہے۔ بھیس بدلتی ہے کہ وہ سپاہیوں کے ساتھ ہم کلام ہو سکے۔ پرمغز جاسوسوں کے ہجوم کو دھوکہ دیتی ہے۔ کیچڑ اور برف سے اٹے ہوئے بازاروں میں میلوں سفر کرتی ہے کہ انقلابی لٹریچر تقسیم کر سکے۔ اپنے اکلوتے بچے کو جو دنیا میں اس کا واحد سہارا تھا، اس تحریک کی بھینٹ چڑھا دیتی ہے اور آخرش تھک کر چور چور گاڑی کے ظالم پہیوں سے لپٹ کر اپنی جان قربان کر دیتی ہے۔۔۔ مگر حالت نزع میں بھی اس کے لبوں پر آزادی کا وہی گیت ہوتا ہے۔
یہ موت اس وقت وقوع پذیر ہوتی ہے جب وہ ایک مقامی اسٹیشن پر اپنے لڑکے کی تقریر کی چھپی ہوئی کاپیاں بغل میں دابے جا رہی تھی۔۔۔ پولیس کے سپاہی اور جاسوس اس کا تعاقب کر رہے ہیں اور اسے ’’چور، چور‘‘ کہہ کر پکار رہے ہیں۔ اس وقت تک وہ سخت خوفزدہ اور سرتاپا ارتعاش تھی اور اپنے آپ سے کہہ رہی تھی، ’’اگر وہ مجھے نہ ماریں تو کتنا اچھا ہو۔۔۔ اگر وہ مجھے مار پیٹ نہ کریں تو کتنا اچھا ہو۔‘‘ مگر ’’چور‘‘ کا لفظ اس کی خفتہ روح کو بیدار کر دیتا ہے۔۔۔ اس کا خوف دور ہو جاتا ہے۔
’’ میں چور نہیں ہوں۔۔۔ تم جھوٹ کہتے ہو۔‘‘ وہ اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے بلند آواز میں چلائی۔ یہ کہتے وقت اس کی نظروں کے سامنے تمام چیزیں انقلابی چکر کی طرح رقص کرنے لگیں اور ہتک کی تلخی نے اس کے دل و دماغ کو گرما دیا۔ اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنا بستہ کھول دیا۔
’’دیکھو! دیکھو! تم سب لوگ ادھر دیکھو!‘‘ وہ چلائی اور اپنے لڑکے کی تقریر کی چھپی ہوئی کاپیوں کے مٹھے ہوا میں لہرائے۔ اپنے کانوں سے اس نے شور میں ان لوگوں کو حیرت کی صدائیں سنیں جو چہار اکناف سے اس کے گرد جمع ہو رہے تھے۔
ماتا اپنے بستے سے تقریر کی کاپیاں نکال کر ہوا میں اچھال دیتی ہے اور بلند آواز میں کہتی ہے، ’’غربت گرسنگی اور بیماری۔۔۔ یہ ہے جو کام، غریب لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ حالات ہمیں جرائم اور بدکاریوں کی طرف کشاں کشاں لے جاتے ہیں۔ ہم سب کے اوپر امراء عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس غرض سے کہ ہم ان کے احکام بجا لائیں۔ پولیس، حکومت، سپاہی سب ان کے ہاتھ میں ہیں۔۔۔ یہ سب لوگ ہمارے درپے آزار ہیں۔ سب چیزیں ہمارے خلاف ہیں۔ ہم روز بروز محنت و مشقت اور غلیظ زندگی میں اپنی جانیں تباہ کر رہے ہیں۔۔۔ دوسرے ہمارے بہائے ہوئے پسینے پر عیش کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں کتوں کی طرح زنجیروں سے جکڑ رکھا ہے۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ خوف کے سائے تلے ہم ہر چیز سے خائف ہیں۔۔۔ ہماری زندگی رات ہے، ایک اندھیری رات! ایک وحشت ناک خواب۔ انہوں نے ہمیں تیز زہر پلا رکھا ہے۔ وہ ہمارا لہو پیتے ہیں۔ افراط عیش انہیں فربہ کر رہا ہے۔۔۔ شیطان حرص کے غلام! کیا وہ نہیں ہیں؟‘‘
یہ ’’درست ہے۔‘‘ لوگوں کی طرف سے جواب آیا۔ اس ہجوم کے پیچھے ماتا ایک مخبر اور دو سپاہیوں کو دیکھ کر جلدی جلدی کاغذوں کے مٹھے تقسیم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ سپاہی پہنچ جاتے ہیں، ’’بنچ پر کھڑ ی ہو جاؤ۔‘‘ سپاہی ماتا کو حکم دیتے ہیں۔
’’میں بہت جلد گرفتار کر لی جاؤں گی۔‘‘
’’یہ ضروری نہیں ہے۔‘‘
’’جلدی بولو! وہ آ رہے ہیں۔‘‘
پولیس کے سپاہی دوڑ کر موقع پر پہنچ جاتے ہیں اور ہجوم کو منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماتا اپنی تقریر جاری رکھتی ہے، ’’لوگو، اپنی تمام قوتوں کو ایک مرکز پر جمع کر لو!‘‘
ایک موٹا سپاہی اپنے سرخ ہاتھ سے اس کا کالر پکڑ کر جھنجھوڑتا ہے، ’’خاموش رہو۔‘‘
اس کی گردن دیوار سے ٹکرائی۔ تھوڑی دیر کے لئے اس کے دل پر خطرے کا تاریک دھواں چھا گیا، مگر فوراً ہی وہ پھر شعلہ فشاں ہوئی۔
اسی لمحے ایک سپاہی دوڑتا ہوا آتا ہے اور اسے اپنا گھونسا تان کر دکھاتے ہوئے کہتا ہے، ’’خاموش بوڑھی مکار!‘‘ یہ سن کر ماتا کی آنکھیں کھلیں، چمکیں۔ اس کے جبڑے کانپے۔ پھسلتے ہوئے پتھروں پر قدم جما کر اور اپنی قوت کے آخری ٹکڑے فراہم کرنے کے بعد وہ چلائی، ’’بیدار روح کو وہ ہر گز فنا نہیں کر سکتے۔‘‘
سپاہی نے اپنا ہاتھ جھٹک کر اس کے منہ پر ضرب لگائی، ایک لمحہ کے لئے کسی سرخ و سیاہ چیز نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ خون کا نمکین ذائقہ اس کے منہ کو بدمزہ کر رہا تھا۔ وہ اسے زد و کوب کرتے گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ اس حالت میں بھی وہ برابر کہے جاتی ہے، ’’تم حق کو خون کے سمندر میں غرق نہیں کر سکتے۔‘‘ پھر وہ اس کا اور اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔
یہ ہے اس عورت کی داستان جو اپنے خاوند کی مارپیٹ سے خمیدہ کمر سیدھی کرنے کے بعد آزادی کی جد و جہد میں شامل ہوئی اور ظالم سپاہیوں کے ہاتھوں دوسرے لوگوں کو خواب غلامی سے بیدار کرنے کی سعی کرتی جان دے گئی۔ اس کا لڑکا پیول شروع شروع میں اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے۔ اپنے باپ کی وفات کے دو ہفتے بعد وہ شراب سے مخمور گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنے باپ کی طرح ایک کونے میں لڑکھڑاتا ہوا بیٹھ کر چلاتا ہے۔
’’کھانا!‘‘
اس کی ماں آئی اور اس کے سر کو اپنی چھاتی سے لگا لیا، مگر پیول نے اسے ایک طرف ہٹا کر کہا، ’’جلدی کرو۔‘‘ ماتا نے غمگین اور محبت بھری آواز میں کہا، ’’بیوقوف لڑکے!‘‘ مگر پیول شراب سے مخمور ہے وہ اسی کو راز حیات سمجھتا ہے کہ اپنے باپ کی پیروی کرے۔ وہ شراب کے نشے میں کہتا ہے، ’’لاؤ! میرے باپ کا پائپ کہاں ہے؟ میں آج سے تمباکو پینا بھی شروع کروں گا۔‘‘ پہلی مرتبہ اس نے شراب کو منہ لگایا ہے۔ گو شراب نے اس کے جسم کو کمزور اور مردہ کر دیا ہے مگر اس کا ضمیر زندہ ہے، جو اسے ملامت کرتا ہے اور اس کے کانوں میں پکارتا ہے کہ وہ شرابی ہے۔۔۔ ایک بیہوش شرابی!
ماں کی محبت اسے سخت تکلیف پہنچاتی ہے۔ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں غم کی جھلک دیکھ کر بہت متاثر ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی صرف ایک خواہش ہے کہ وہ روئے اور خوب روئے۔ اس خواہش پر غلبہ پانے کے لئے وہ اپنے آپ کو زیادہ مخمور کرتا ہے، مگر ماں اسے پیار سے کہتی ہے، ’’بیٹا، تم نے ایسا برا کام کیوں کیا۔۔۔ تمہیں یہ چاہیئے نہیں تھا۔‘‘ تھوڑی دیر کے بعد ماتا اسے بستر پر لٹا دیتی ہے اور اس کی دہکتی پیشانی پر ٹھنڈے پانی سے تر تو لیا رکھ دیتی ہے۔ اس پر پیول کو قدرے ہوش آتا ہے اور وہ سوچتا ہے، ’’میرا خیال ہے کہ میں نے قبل از وقت شراب نوشی شروع کر دی ہے۔ دوسرے بھی تو پیتے ہیں۔ انہیں کچھ نہیں ہوتا، پر میں بیمار پڑ گیا ہوں۔‘‘
کمرے کے کسی حصے سے ماتا کی غمگین آواز سنائی دی، تم نے ابھی سے شراب پینا شروع کر دی ہے۔ اب تم میری خبر گیری کیسے کر سکو گے۔‘‘ پیول آنکھیں بند کر کے جواب دیتا ہے، ’’ہر شخص پیتا ہے۔‘‘
’’ہر شخص پیتا ہے۔‘‘ ان مختصر الفاظ میں گورکی نے ان تمام مزدوروں کا صحیح نقشہ کھینچ دیا ہے جو مشقت سے چور چور ہو کر کسی ارضی لذت کے خواہاں تھے۔ وہ شراب کیوں پیتے تھے؟ اس کے جواب کے لئے گورکی کے اپنے الفاظ موجود ہیں، ’’سالہا سال کی جمع شدہ تھکاوٹ نے ان کی بھوک چھین لی تھی۔ کچھ کھا سکنے کے لئے وہ شراب نوشی کرتے۔۔۔ اپنے کمزور معدوں سے کام لینے کی خاطر ’’ودوکا‘‘ کا جھلس دینے والا چابک استعمال کرتے تھے۔ اپنے بیٹے کا جواب سن کر ماتا ٹھنڈی سانس بھرتی ہے کیونکہ اسے معلوم ہے اس کا لڑکا درست کہتا ہے۔ ماتا کو اچھی طرح علم ہے کہ شراب خانے کے سوا مردوں کے لئے کوئی اور جگہ نہیں، جہاں وہ اپنا غم غلط کر سکیں، مگر پھر بھی وہ اپنے بچے کو نصیحت کرتی ہے کہ اسے شراب نوشی ترک کر دینی چاہیئے۔ اس لئے کہ اس کے باپ نے اس کے حصے کی پی کر اسے کافی سے زیادہ تنگ کیا تھا۔
پیول کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ ماں کی غمگین اور ترحم انگیز گفتگو سن کر پیول نے خیال کیا کہ اس کی ماں اپنے خاوند کی بے جا مارپیٹ سے بچنے کے لئے ہمیشہ چپ چاپ رہا کرتی تھی۔ وہ خود چونکہ اپنے والد کی خشمگیں نگاہوں سے بچنے کی خاطر ہمیشہ گھر سے غیر حاضر رہا کرتا تھا، ا س لئے اسے اپنی ماں کو جاننے کا بہت کم اتفاق ہوا تھا، مگر اب جوں جوں اسے ہوش آنے لگا، اس نے اپنی ماں کی طرف غور سے دیکھنا شروع کیا۔
اس کی ماں لانبے قد کی اور اوپر سے ذرا جھکی ہوئی تھی۔ اس کا بھاری جسم سالہا سال کی ان تھک محنت اور خاوند کی مارپیٹ سے اب بڑی مشکل سے ہلتا تھا۔ وہ کمرے میں اس انداز سے ٹہل رہی تھی کہ معلوم ہوتا تھا ابھی گر پڑے گی۔ یہ دیکھ کر اور اس پر غور کرنے کے بعد پیول اسی دم شراب کی لعنت دور کرنے کا تہیہ کر لیتا ہے اور پھر کبھی مے نوشی نہیں کرتا۔
وہ مے نوشی نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ ایک کتاب اس کے خفتہ ساز دل پر مضراب کا کام دیتی ہے اور اس کے پیداکردہ نغمات سے متاثر ہو کر وہ انقلاب پسند جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔۔۔ شرابی قصر آزادی کا معمار بن جاتا ہے۔ روس کے گلی کوچے اس کی صدائے انتقام سے گونج اٹھتے ہیں۔ پیول اپنے رفیقوں سمیت پکڑا جاتا ہے اور عدالت کے روبرو پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں وہ اپنا بیان دیتا ہے۔
’’ہم اشتراکی ہیں۔۔۔ سرمائے کے دشمن، جو لوگوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرتا ہے، جو انسان کو انسان کے خلاف لڑنے پر آمادہ کرتا ہے۔۔۔ ہمارے نزدیک وہ سماج جو انسان کو اپنی دولت بڑھانے کا آلہ تصور کرتا ہے، غیر انسانی ہے۔ ہم لڑنا چاہتے ہیں اور ہر اس بندش کے خلاف جو انسان کو جکڑے ہوئے ہے لڑیں گے، خواہ وہ اخلاقی ہو یا جسمانی۔۔۔ ہم مزدور ہیں۔۔۔ و ہ لوگ جن کی مشقت ننھے کھلونوں سے لے کر دیوقامت مشینیں تک تیار کرتی ہے۔ ہم وہ افراد ہیں جو اپنی عزت نفس کو برقرار رکھنے کے حق سے محروم کر دیئے گئے ہیں۔ ہر شخص ہمیں استعمال کرنے میں کوشاں ہے اور اپنے آرام کے لئے ہمارا ہر وقت استعمال کیا جاتا ہے۔۔۔
اب ہم اتنی آزادی کے خواہاں ہیں جو ہمارے لئے تمام قوتوں کو مسخر کرنا ممکن بنا دے۔ ہمارا مطمع حیات بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ تمام اختیار عوام کے ہاتھوں میں، پیداوار کے تمام ذرائع عوام کے لئے، سب کے لئے کام کرنا فرض۔۔۔ انفرادی سرمائے کی بیخ کنی اور بس۔۔۔ آپ دیکھتے ہیں، ہم باغی نہیں ہیں۔‘‘
جج آغوش جہالت میں پرورش پائے ہوئے شخص کے منہ سے فاضل مقرر ایسے الفاظ سن کر بہت حیران ہوتا ہے، مگر فوراً ہی اسے اصل موضوع کی طرف پلٹنے کا حکم دیتا ہے۔ پیول تھوڑی دیر کے بعد اپنی تقریر شروع کرتا ہے، ’’ہم انقلابی ہیں اور اس وقت تک انقلابی رہیں گے جب تک ذاتی سرمائے کا وجود باقی ہے، جب تک چند افراد حکومت کرتے ہیں اور باقی صرف محنت و مشقت کرتے ہیں۔۔۔ ہم فتح یاب ہوں گے۔۔۔ ہم مزدور یقیناً جیتیں گے۔ تمہاری سوسائٹی اتنی طاقتور نہیں ہے، جتنی کہ تم سمجھ رہے ہو! یہی سرمایہ جس کی حفاظت اور پیدائش کے لئے سوسائٹی لاکھوں انسان قربان کرتی ہے۔۔۔ یہی قوت جو اسے ہم پر حکومت کرنے کا اختیار بخشتی ہے، اس کے افراد کی جسمانی و اخلاقی تباہی کا باعث ہے۔ سرمایہ کے لئے انتہائی حفاظت درکار ہے اور درحقیقت تم سب ہمارے حکام ہم سے زیادہ غلام ہو۔۔۔
تم روحانی لحاظ سے غلامی کی زندگی بسر کرتے ہو اور ہم جسمانی لحاظ سے۔۔۔ تمہاری قوت۔۔۔ تمہارا سرمایہ تمہیں کئی حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، جو ایک دوسرے کو نگلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ہماری قوت ایک زندہ طاقت ہے۔ جس کی بنیاد مزدوروں کی ہمیشہ بڑھنے والی بیداری ہے۔ تمہارا ہر کام جرم سے وابستہ ہے۔ ا س لئے کہ اس کا مقصد عوام کو غلامی کے جال میں پھنسانا ہے۔ ہمارا کام دنیا کو ان تمام مہیب دیوؤں سے نجات دلانا ہے جو تمہاری حرص کے پیدا کردہ ہیں۔ تم نے لوگوں سے زندگی چھین کر انہیں کچل دیا ہے۔ اشتراکیت تمام دنیا کو آپس میں جوڑ دے گی، جو تمہارے بوجھ تلے دب کر شکستہ ہو چکی ہے۔۔۔ اور یہ ضرور ہوگا!‘‘
پیول یہاں تک پہنچ کر ایک لمحہ کے لئے ٹھہرتا ہے او رپھر آہستہ لہجہ میں کہتا ہے، ’’اور یہ ضرور ہوگا!‘‘
پیول کے رفقاء میں اینڈری کا کردار بہت دلچسپ ہے۔ بات بات پر مزاحیہ نوک جھونک کرنے میں اس کو مزا آتا ہے۔ عدالت میں پیش ہے، سائبیریا کے یخ بستہ میدان آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں، مگر وہ ججوں سے بھی مذاق کرنے سے باز نہیں آتا،
اینڈری اٹھا، اس نے اپنے جسم کو حرکت دی۔ ججوں کی طرف کنکھیوں سے دیکھا اور کہنے لگا، ’’معزز مدعا علیہ حضرات۔۔۔‘‘
’’عدالت تمہارے سامنے ہے نہ کہ مدعا علیہ‘‘
اینڈری کے چہرے اور گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عدالت کو تنگ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے لانبے ہاتھوں سے اپنے سر کو تھپکا اور کہا، ’’سچ مچ؟ مگر میرا خیال کچھ اور ہے تم جج نہیں ہو محض مدعا علیہ ہو۔۔۔‘‘
یہ سن کر ایک جج خشک لہجے میں پکارتا ہے، ’’از راہ عنایت وہی بیان دو جو اس مقدمہ سے متعلق ہے۔‘‘
’’جو مقدمے سے متعلق ہے؟ بہت خوب! چلئے میں نے یقین کر لیا کہ آپ واقعی جج ہیں۔۔۔ خود اختیار اور ایماندار!‘‘
’’عدالت یہ کردار نگاری نہیں چاہتی۔‘‘
’’اس کردار نگاری کی ضرورت نہیں؟ اچھا میں اپنا بیان جاری رکھتا ہوں۔۔۔ تم وہ افراد ہو جو اپنے اور اجنبیوں کے درمیان کوئی تمیزنہیں کرتے۔ تم آزاد ہو۔ اب یہاں دو فریق تمہارے روبرو کھڑے ہیں۔ ایک شکایت کرتا ہے۔ ’مجھے اس نے لوٹ کر برباد کر دیا ہے۔ ‘ اور دوسرا جواب دیتا ہے۔ ’مجھے لوٹنے کا حق ہے۔ اس لئے کہ میرے بازو موجود ہیں۔۔۔ ۔‘‘
عدالت پھر اسے خاموش رہنے کا حکم دیتی ہے۔ اس لئے کہ وہ اس قسم کی گفتگو سننا پسند نہیں کرتی۔ افسانے کا یہ مزاحیہ کردار چند اور الفاظ کہنے کے بعد اپنا بیان بند کر دیتا ہے۔
’’جو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ میرا رفیق بتا چکا ہے۔۔۔ باقی پھر کہا جائے گا۔۔۔ وقت پر دوسرے گوش گزار کر دیں گے۔۔۔‘‘
ان سیاسی قیدیوں یعنی پیول کے رفقاء میں جو سائبیریا میں جلاوطن کر دیے جاتے ہیں، ایک نوجوان کا آتشیں کردار بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے مختصر بیان کی نفسیات مطالعہ کرنے کے بعد ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک جواں قلب میں آزادی کی آگ کس تیزی سے بھڑکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس کے الفاظ میں کم تجربہ کاری اور بچپن کی جھلک بھی دیکھتے ہیں،
ننھا میزن شامپین کی بوتل کے کاگ کی طرح اٹھا اور لرزاں آواز میں کہنے لگا، ’’میں۔۔۔ میں قسم کھاتا ہوں۔۔۔ مجھے معلوم ہے تم نے مجھے ملزم قرار دیا ہے۔۔۔‘‘ میزن کا سانس اکھڑ گیا اور چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں اس کے تمام چہرے کو نگلتی دکھائی دے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر بلند آواز میں بولا، میں۔۔۔ اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ تم مجھے خواہ کہیں بھیج دو۔۔۔ میں فرار ہو جاؤں گا۔۔۔ واپس آ جاؤں گا۔۔۔ ہمیشہ یہی کام کروں گا۔۔۔ اپنی زندگی بھر۔۔۔ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے!‘‘
ماتا کے تمام کرداروں سے فرداً فرداً بحث ایک طویل مضمون کی محتاج ہے۔ اس مختصر مضمون میں حتی الوسع ماتا پر ہر پہلو سے روشنی ڈالنے کی سعی کی گئی ہے مگر پھر بھی یہ مضمون تشنہ ہے۔ اب ہم گورکی کے فن منظر کشی کی طرف پلٹتے ہیں۔ یہاں ماتا میں سے ہم مثال کے طور پر چند مناظر پیش کرتے ہیں جو قارئین کے لئے یقیناً دلچسپ ہوں گے۔ ماتا کے منظر افتتاحیہ میں گورکی کا قلم کارخانہ کی طرف رخ کرنے والے مزدوروں کی تصویر ان زندہ الفاظ میں پیش کرتا ہے،
’’ہر روز کارخانے کی سیٹی، مزدوروں کی غلیظ اور دھوئیں سے پر، فضا میں کانپتی آواز میں غراتی، جس پر بھاپ کے غلام اپنے چھوٹے اور بدنما گھروں سے نکلنا شروع ہو جاتے۔ غمگین چہروں کے ساتھ وہ خوف زدہ وحشیوں کی طرح تیز قدم بڑھاتے۔ ان کے اعضا ناکافی نیند کی وجہ سے اکڑے ہوتے۔ صبح کی دھندلی روشنی میں وہ تنگ گلیوں اور کچی سڑکوں سے گزرتے ہوئے اس سنگین پنجرے کی طرف بڑھتے جو ان کے استقبال کا منتظر ہوتا۔۔۔ جس کی بیسیوں زرد، بھدی اور چوکور آنکھیں کیچڑ سے بھری ہوئی سڑک کو روشن کر رہی ہوتیں۔ کیچڑ کے چھینٹے ان کے پیروں پر اس طرح گرتے گویا ان کا مضحکہ اڑا رہے ہیں۔ فضا بھدی، خواب زدہ آوازوں اور گالیوں سے معمور ہوتی۔ ان کے استقبال کے لئے مشینوں کی بھاری گڑگڑاہٹ اور بھاپ کی غیر مطمئن چیخ پکار ہوا میں تیر رہی ہوتی۔۔۔ دراز قامت دودکش دھوئیں کے گہرے اور موٹے بادل اپنے حلق سے نکالنا شروع کر دیتے۔‘‘
یہ تو ہے مزدوروں کی کارخانوں کی طرف روانہ ہونے کی تصویر، اب ان کی واپسی کا نقشہ بھی گورکی کا معجز نگار قلم یوں کھینچتا ہے،
’’شام کو سورج غروب ہوتے وقت سرخ کرنیں گھروں کی کھڑکیوں پر چمک رہی ہوتیں۔ کارخانہ اپنے مزدوروں کو جلی ہوئی راکھ کے مانند باہر پھینک دیتا۔ اب وہ پھر ان ہی بازاروں سے اپنے دھوئیں میں لپٹے ہوئے چہرے اور گرسنہ دانتوں کی چمک کی نمائش کرتے مشین کے تیل کی غلیظ بوکو پھیلاتے گزرتے، مگر اب ان کی آوازوں میں خوشی کی جھلک پائی جاتی۔۔۔ مشقت کی سزا اس دن کے لئے ختم ہو چکی تھی۔ آرام کی چند گھڑیاں اور روکھا سوکھا کھانا گھر پر ان کا انتظار کر رہا تھا۔
دن کارخانہ نگل گیا اور مشین نے ان انسانوں کے اعضاء سے حسب ضرورت طاقت چوس لی۔ اس طرح ایک مکمل دن زندگی سے جذب کر لیا گیا جس کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ مزدور اس حیوانی مشقت کے باوجود کیونکر زندہ رہتا ہے۔ اس کے جواب کے لئے گورکی کے الفاظ موجود ہیں، ’’انسان نے قبر کی طرف قدم بڑھائے، مگر جب اس کو نزدیک ہی آرام کی راحتیں اور مے خانوں کی مسرتیں نظر آئیں تو وہ مطمئن ہو گیا۔‘‘
یہ ہمیں بھی معلوم تھا، مگر گورکی نے اسی خیال کو اپنے سحر آفریں الفاظ میں پیش کر دیا۔ مرصع الفاظ سے اپنے فن کی زیبائش کرنا۔۔۔ یہی گورکی کا راز اور اس کی فقید المثال صنعت ہے۔ ان الفاظ پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد اس سحرکار کی ناقابل نقل فن کاری عیاں ہو جاتی ہے اور پھر کسی مزید تفصیل کی حاجت نہیں رہتی۔
تعطیل کے دنوں میں گورکی نے برگشتہ بخت اور واژگوں نصیب مزدوروں کی حیات اس پیرائے میں بیان کی ہے کہ ایک کم عقل بچہ بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ دراصل گورکی وہی بیان کرتا ہے جو اس سے پیشتر ہمارے دل میں موجود ہوتا ہے، مگر اس کے الفاظ پہلو میں اس سوئے ہوئے احساس کو اپنے ترنم سے بیدار کر دیتے ہیں،
’’تعطیل کے روز مزدور دن کے دس بجے تک سوئے رہتے۔ بوڑھے اور شادی شدہ لوگ بہترین کپڑے پہن کر نوجوانوں کو گرجا میں عبادت کے لئے نہ جانے کی بنا پر برا بھلا کہتے۔ پادری کا خطبہ سننے کے لئے جاتے، گرجے سے واپس آ کر وہ کچھ کھا کر پھر سو جاتے۔۔۔ شام کے وقت وہ سڑکوں پر آوارہ چکر لگاتے جن کے پاس بڑے بوٹ ہوتے، وہ انہیں پہن لیتے خواہ بازار صاف ہی ہوں۔ جن کے پاس چھاتے موجود ہوتے وہ انہیں اپنے ساتھ ساتھ لئے پھرتے، خواہ آسمان بالکل ابرآلود نہ ہو۔‘‘
یہ پڑھنے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسی نکمی چیزوں کی کیوں نمائش کرتے ہیں؟ گورکی فوراً ہی جواب دیتا ہے، ’’ہر شخص یہی خواہش کرتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے خواہ وہ کتنا ہی معمولی اور حقیر کیوں نہ ہو، اپنے ہمسائے سے زیادہ معزز دکھائی دے۔‘‘ پھر وہ ان مزدوروں کی آپس میں لڑنے جھگڑنے کی وجہ بیان کرتا ہے۔ کتنے سادہ الفاظ ہیں، جو دل و دماغ میں سے گزرتے روح میں جذب ہو جاتے ہیں، ’’روزانہ مشقت سے تھکے ہوئے لوگ شراب کا کثرت سے استعمال کرتے، جس سے ان کے دلوں میں ایک ناقابل بیان بے چینی پیدا ہو جاتی جو باہر نکلنے کے لئے راستہ مانگتی۔ اس خاموش نہ ہونے والے اضطراب کا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے وہ معمولی سے معمولی واقعات کو اہمیت دیتے اور وحشیوں کی طرح حقیر سے حقیر چیز پر ایک دوسرے سے جنگ کرنے لگ جاتے۔ یہ کینہ ان کے د لوں میں ناقابل علاج تکان کی طرح جو ان کے اعضاء میں گھر کر چکا تھا بڑھتا رہتا۔۔۔ وہ اس روحانی بیماری کو ساتھ لے کر پیدا ہوئے تھے جو انہیں اپنے والدین سے ورثہ میں ملی تھی۔‘‘
گورکی اسی جماعت کا ایک برہنہ پا وگرسنہ شکم فرد تھا اور وہ اب اسی ملت کاسب سے بڑا مفکر، سحر کار مصور، پیغام بر، قصہ خواں، افسانہ نویس اور تمثیل نگار ہے۔
گورکی جن مفلس، مصیبت زدہ اور بدچلن روسیوں کا ہم سے تعارف کراتا ہے ان کی فطرت، عزت اور بری عادتوں کی زنجیروں میں ایسی بری طرح جکڑی ہوتی ہے، ان کے دلوں کو برے اعمال اور ارادوں نے ایسے سیاہ کر رکھا ہے، ان کے ماحول میں راہ راست پر چلنے کی ترغیب دلانے والے اثرات اتنے کم اور کمزور ہیں کہ ہمیں ان کے انسان ہونے میں کیا، زندہ رہنے پر تعجب ہوتا ہے لیکن انسانیت کی اس عبرت انگیز بربادی میں بھی ایک روشنی کبھی کبھی نظر آ جاتی ہے، جس پر اگر اپنی نظر قائم رکھ سکیں تو گورکی کے ویرانے آباد معلوم ہونے لگتے ہیں۔
اس کے بیماروں میں صحت کے وہ آثار، مردوں میں زندگی کی وہ علامت ظاہر ہونے لگتی ہیں جو ہم کو یقین دلاتی ہیں کہ انسانیت کا جوہر کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ اس کے دشمن اسے چاہے جتنا مرضی چھپائیں وہ ہماری نظروں سے بالکل غائب نہیں ہو سکتا اور جب کبھی وہ نظر آئے گا تو اس شان سے کہ ہم دوسروں کی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اس سے روشنی پائیں گے۔ گورکی نے انسانیت کا جو جوہر دریافت کیا ہے وہ انسانی ہمدردی ہے ایک جذبہ جو پست حیوانی زندگی کی تاریکی کو اس طرح ریزہ ریزہ کر دیتا ہے جیسے بجلی کالی گھٹا کے اندھیرے کو۔
(مقدمہ گورکی کے افسانے، رسالہ اردو)
(1) گورکی اپنے اس محسن کا بہت احترام کرتا ہے، چنانچہ اس نے اپنے افسانوں کا ایک مجموعہ مسٹر ایم اے لینن کے نام سے معنون کیا ہے۔
(2) گورکی کے لفظی معنی کڑوا یا ملول ہے۔
(3) ولادی میر کارلنکو، جنوبی روس میں ۱۹۵۳ء میں پیدا ہوا۔ روس کے دیگر ادباء کی طرح وہ حصول تعلیم سے سیاسی وجوہ کی بنا پر تشنہ رہا۔ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی وجہ سے اسے ماسکو کے زراعتی سکول کو خیرباد کہنا پڑا۔ اسے ۶ سال کا طویل عرصہ سائبیریا کے یخ بستہ میدانوں میں کاٹنا پڑا۔ زمانہ اسیری کے بعد وہ موضع نزہنی میں اقامت پذیر ہوا۔ جہاں وہ مدت تک ایک رسالہ کی ادارت کے فرائض سرانجام دیتا رہا۔ اسی زمانہ میں گورکی سے اس کی ملاقات ہوئی۔ کارلنکو روسی ادب میں خاص شہرت رکھتا ہے۔
(4) امریکہ کا مشہور مزاح نگار
(5) چیخوف نے بھی گورکی کی اس خصوصیت کا تذکرہ اپنے ایک خط میں کیا ہے جو اس نے گورکی کو لکھا تھا۔
(6) ایک انگریز نقاد نے گورکی پر نقد و تبصرہ کرتے وقت یہ کہا ہے۔
(7) تھری مین کا ہیرو
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.